اسلامى تہذيب و ثقافت
 0%
0%
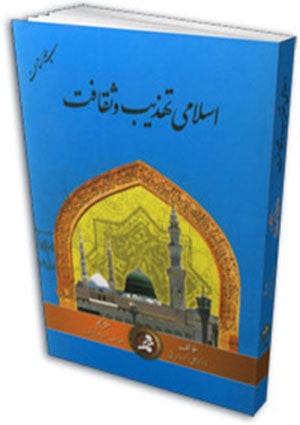 مؤلف: ڈاكٹر على اكبر ولايتي
مؤلف: ڈاكٹر على اكبر ولايتي
زمرہ جات: متفرق کتب
صفحے: 375
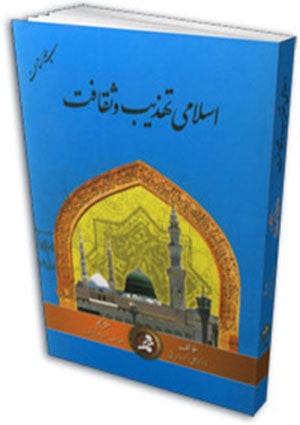
مؤلف: ڈاكٹر على اكبر ولايتي
زمرہ جات:
مشاہدے: 155351
ڈاؤنلوڈ: 6626
تبصرے:
- مقدمہ
- تمہيد
- مرحلہ 1: اسلامى بيداري
- مرحلہ 2: اسلامى حكومت كى تشكيل
- مرحلہ 3: اسلام كى نشر و اشاعت
- مرحلہ 4: اسلامى تہذيب و تمدن كى تجديد
- پہلا باب
- كلى مباحث
- 1_ علمى بنياد اور تاريخى سرچشمے
- تعريفيں
- تہذيب كا ثقافت سے ربط
- تہذيبوں كى پيدايش اور ترقى ميں مؤثر اسباب
- تہذيبوں كے انحطاط اور زوال كے اسباب
- اخلاق ، ثقافت، تہذيب اور قانون
- دوسرا باب
- اسلامى تمدن كى تشكيل كا پس منظر
- 1 اسلام ميں علم و دانش كا مقام
- اسلامى تہذيب و تمدن ميں تاريخ كتابت پر ايك نظر
- 2_ علوم كا منتقل ہونا اور اہل علم و دانش كى دنيائے اسلام ميں شموليت
- 3_ترجمے كى تحريك
- (الف) ہارون الرشيد كا دور
- ب) مامون كا دور ( حكومت 218 _ 198قمرى )
- ج) مامون كے بعد كا دور
- د) تحريك ترجمہ كا اختتام
- 4_ اسلامى تمدن ميں علمى مراكز
- تيسرا باب
- اسلامى تمدن ميں علوم كى پيش رفت
- علوم كى درجہ بندي
- الف) غير اسلامى علوم
- 1) رياضيات
- 2) نجوم
- 3_ فزكس اور ميكانيات
- 4 ) طب
- 5_ كيميا
- 6_ فلسفہ
- 7) منطق
- تاريخ اور تاريخ نگاري
- 9 ) جغرافيا
- پہلا دور (تيسرى اور چوتھى صدي)
- دوسرا دور (پانچويں صدي)
- تيسرا دور(چھٹى صدى سے دسويں صدى تك )
- چوتھا دور (گيارہويں سے تيرہويں صدى تك)
- ادب
- الف) عربى ادب
- ب) فارسى ادب
- 1) فارسى شعر
- 2) فارسى نثر
- ج) تركى ادب
- ب ) اسلامى علوم
- 1) قرائت
- 2 _ تفسير
- 3_ حديث
- 4 _ فقہ
- الف) شيعہ فقہ
- ب) اہل سنت كى فقہ اور تغير و تبدل كے ادوار
- 5_ اصول
- 6_ كلام
- 7_ تصوف، عرفان اورفتوت
- چوتھا باب
- اسلامى تہذيب ميں انتظامي اور اجتماعى ادارے
- 1) ديوان
- ديوان خراج يا استيفائ
- ديوان بريد(ڈاك اور خبر رسانى كا نظام)
- ديوان انشاء
- ديوان جيش
- ديوان بيت المال
- ديوان نفقات
- ديوان اقطاع
- ديوان عرض
- ديوان العمائر يا ديوا ن الابنية المعمورة
- ديوان مظالم
- 2 ) خراج
- 3)حسبہ(احتساب كا نظام)
- پانچواں باب
- اسلامى تہذيب و تمدن ميں فن و ہنر
- 1_ فن معمارى ، مصورى ، خطاطى اور ظروف سازى كى صنعتيں
- 2_ علم موسيقي
- چھٹا باب
- اسلامى تہذيب كےمغربي تہذيب پر اثرات
- 1_ عقلى علوم ، اسلامى فلسفہ اور الہى علوم كے مغربى تہذيب پر اثرات
- 2_ اسلامى طب كے مغربى تہذيب پراثرات
- 3_ اسلامى رياضيات كے مغربى تہذيب پر اثرات
- 4_ اسلامى علم فلكيات كے مغربى تہذيب پر اثرات
- 5_ اسلامى جغرافيہ كے مغربى تہذيب پر اثرات
- 6_ اسلامى ہنر و فن كا يورپ ميں نفوذ
- اقوام اسلامى كے فن مصور ى كے مغربى فن مصور ى پر اثرات
- اسلامى موسيقى كے مغربى موسيقى ميں اثرات
- اسلامى معمارى كے يورپى معمارى پر اثرات اور نقوش
- ساتواں باب
- اسلامى تہذيب كے جمود كے اندرونى اور بيرونى اسباب
- الف : بيرونى اسباب
- 1_ صليبى جنگيں
- 2_ منگولوں كى آمد
- منگولوں كا حملہ اور اسكے نتائج
- اسلامى دنيا پر منگولوں كا حملہ
- منگولوں كى پيش قدمي
- چنگيز كے جانشين اور عالم اسلام پر حملوں كا تسلسل
- منگولوں كى پيش قدمى كا اختتام او ر ايلخانى حكومت كى تشكيل
- منگولوں كے دور ميں اسلامى دنيا كى تہذيبى صورت حال كا جائزہ
- 3: سقوط اندلس
- اندلس مسلمانوں كى فتح سے پہلے
- مسلمانوں كے ہاتھوں اندلس كى فتح
- اسلامى حكومت كے دور ميں اندلس كى سياسى تاريخ
- الف) اندلس دمشق كى مركزى اموى حكومت كا ايك حصہ (132_98 قمرى / 755_716 )عيسوي
- ب) اندلس پر اموى حاكموں كا جداگانہ سلسلہ (422_ 138 قمري) / (1031 _ 755عيسوي)
- ج) اندلس ميں جاگير دارانہ دور 898_ 422 قمري/ 1492_1031عيسوي
- اندلس كے علمى اور ثقافتى حالات كا جائزہ
- عيسائيوں كے ہاتھوں اندلس كے سقوط كے اسباب
- الف: اندلس ميں مسلمانوں كے زوال ميں موثر اندرونى اسباب
- ب: سقوط اندلس كے بيرونى اسباب
- ج: اسلامى اندلس كے سقوط كے سياسى جغرافيائي geopolitical اسباب
- نتيجہ بحث
- ب:اندرونى اسباب
- 1_ استبداد( آمريت)
- آمريت يا استبداد ( Dictatorship )كى تعريف
- اسلامى ممالك ميں آمريت كا سرچشمہ
- 1_ اقتصاد اور آبپاشى كا طريقہ كار
- 2 _ عمومى مالكيت
- 3_بيوركريسى (ديوان سالاري)
- آمريت كے نتائج
- اسلامى معاشروں ميں آمريت
- 2_ دنيا پرستى ،قدامت پسندى اور حقيقى اسلام سے دوري
- الف: دنيا پرستي
- سلسلہ بنى اميہ كا آغاز اورعيش و عشرت كى ابتدائ
- خلفاء اورا مراء كى بے پناہ ثروت اور اسكے نتائج
- ب: قدامت پرستي
- ج ) اسلامى دنيا ميں عقل اور عقل دشمن تحريكيں
- آٹھواں باب
- بيدارى عالم اسلام كى نشا ة ثانيہ
- 1_ صفوي
- الف) صفويوں كا ظہور
- ب) صفوى حكومت كى تشكيل
- ج) استحكام كا مرحلہ
- د) زمانہ عروج
- خارجہ روابط
- الف) ہمسايوں كے ساتھ روابط
- صفوى دور كى تہذيب و تمدن
- مذہب شيعہ كوسركارى قرار دينا اور اسكے نتائج
- ادبيات
- مدارس اور علوم
- معماري
- كپڑا اور قالين بننے كا كام
- فوجى اسلحہ
- صفويوں كا دفترى نظام
- صفويوں كا زوال
- عثمانى حكومت
- امارت سے بادشاہت تك
- 3_مغل سلاطين
- سياسى تاريخ
- مغلوں كے صفويوں سے روابط
- مغلوں كے يورپى حكومتوں سے تعلقات
- مغلوں كا اداراتى اور سياسى نظام
- فارسى ادبيات
- مسلمان عرفا اور انكى ہندوستان ميں خدمات
- ہندوستان كے اسلامى ہنر و فنون
- فن مصورى
- نواں باب
- اسلامى تہذيب و تمدن كے جمود اور زوال كے آخرى اسباب
- 1) استعمار قديم و جديد
- استعمار قديم
- استعمار كا مفہوم اور تاريخ
- استعمار كے وجود ميں آنے كے اسباب
- ايشيا ميں استعمار
- مشرقى وسطى اور خليج فارس ميں استعمار
- استعمار جديد
- ملٹى نيشنل ( كثير القومى ) كمپنياں
- بين الاقوامى مالياتى ادارے
- عالمگير يت(2) اور اسكے نتائج
- 2_مشرق شناسي
- صہيونيزم
- دسواں باب
- اسلامى بيداري
- 1) عرب دنيا ميں اسلامى بيدارى
- 2_ ايران ميں اسلامى بيداري
- گيارھواں باب
- مغربى تہذيب پر نقد و نظر
- 1_ مغربى مفكرين كى آراء ميں مغربى تہذيب پر تنقيد
- ايرانى اور عرب دانشوروں كى آراء ميں مغربى تہذيب پر تنقيد
- منابع و مآخذ






