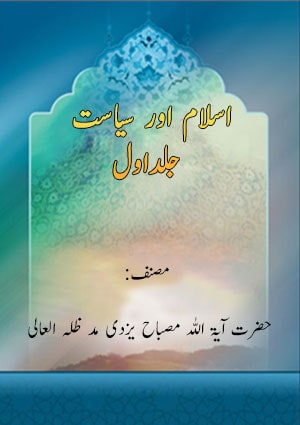پہلا جلسہ
اسلامی سیاست کے سلسلے میں چند اہم سوالات
مقدمہ ۱
بے شک ہمارے اسلامی نظام اور انقلاب کے ثمرات میں سے ایک نماز جمعہ بھی ہے جس کے امت اسلامی کے لئے بہت سے فوائد ہیں مثلاً جس کا ایک ضمنی فائدہ مومنین کو ضروری چیزوں سے آگاہ کرنا ہے ، نماز جمعہ کے خطبوں سے قبل یا نماز جمعہ اور نماز عصر کے درمیان تقاریر کا سلسلہ لوگوں کے لئے بہت مفید ہے ، چنانچہ شروع انقلاب سے آج تک مختلف اساتید دانشمندان اور خطباء کے ذریعہ مختلف موضوعات منجملہ اعتقادی ‘تربیتی ‘ اقتصادی‘ وغیرہ جیسے عظیم اور مہم مسائل پرنماز جمعہ پڑھنے والوں کے درمیان یہ گفتگو ہوتی رہی ہے اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ بھی دوسرے لوگوں تک یہ آواز پہونچتی رہی ہے۔
ہم نے بھی ”اعتقادی نظام اور ارزش اسلام میں توحید کی اہمیت“ کے موضوع پر تقریریں کیں ہیں ، جو الحمد للہ چھپ کر قارئین کرام تک پہونچ چکی ہیں ، فی الحال بعض احباب اور دوستوں کی فرمایش اور ان کے اصرار پر” اسلام کے سیاسی نظریات “ کے عنوان کے تحت چند جلسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور امیدوار ہیں کہ خداوند عالم اس سلسلہ میں ہماری مدد فرمائے، او رجو بھی اس کی مرضی ہو اور امت اسلام کے لئے مفید ہو وہ ہمیں الھام کرے ، او ر ہماری زبان پر جاری کرے ، تاکہ شھید پرور اور حزب اللٰھی امت تک ہم اس کو پہونچا سکیں ، ہماری اس بحث کا عنوان بہت وسیع ہے ، اس کے اندر مختلف موضوعات کی بحثیں کی جاسکتی ہیں چاہے وہ عمیق ہوں یا سادی اور رواں ۔
اگرچہ اس سلسلہ میں امام خمینی کی تحریک کے آغاز (یعنی۱۳۴۱ھجری شمشی )سے لے کر آج تک بہت سی گفتگو ہوتی رہی ہے اور مضامین و کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ، اس طرح بہت سی تقاریر بھی ہوتی رہیں ہیں ، لیکن معاشرہ کے متوسط فہم لوگوں کے لئے بہت ہی کم اس طرح کے منظم مطالب بیان کئے گئے ہیں ، بہرحال احباب کا اصرا ر تھا کہ ان مطالب کو اس ترتیب سے بیان کیا جائے تاکہ سبھی لوگ اس سے استفادہ کرسکیں ،اور مختلف لوگوں کی خصوصا جوان طبقہ کی ضرورت کو پورا کرسکے ، الحمد للہ ہماری قوم تمدن کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے ، خصوصاً آخری چند سالوں میں ہمارے معاشرے اور ماحول نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ، اور بہت سے دقیق و عمیق مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، بہر حال علمی او ر ادبی زبان ، علمی مراکز (یونیورسٹی اور حوزات علمیہ )سے مخصوص ہے ، اور اگر عوام کے لئے گفتگو کرنا ہو تی ہے تو حتی المقدور علمی اصطلاحات نہیں ہونی چاہیئے تاکہ اکثر لوگ (چونکہ مطالعہ نہیں ہے ) ان ابحاث سے فائدہ اٹھا سکیں ، البتہ اس بات کی توجہ رکھنی چاہیے کہ اسلام کے سیاسی فلسفہ کے تحت جو گفتگو کی جائے گی اتنی مفصل بحث ہے جس کو ۱ ۰۰ جلسوں میں بھی بیان کرنا مشکل کام ہے ، اس وجہ سے ہم اپنے وقت اور جلسات کی محدودیت کی بنا پر کچھ منتخب مسائل کو چھیڑیں گے ، او ر جن مسائل کی زیادہ ضرورہے، اور جن کے سلسلہ میں سوالات اور شبھات کئے جاتے ہیں ،ان کے بارے میں بحث کریں گے۔
یہ توجہ رہے کہ ہمارا موضوع بنام”اسلام کا سیاسی فلسفہ “ تین کلموں سے مرکب ہے جس کے ہر ایک کلمہ کے لئے مفصل بحث درکار ہے اور سیاسی فلسفہ کی متعدداصطلاح ہیں (مثلاًعلم سیاست کا فلسفہ وعلم سیاست کے مقابل میں فلسفہ سیاسی) لیکن فلسفہ سیاسی سے ہماری یھاں مراد حکومت و سیاست کے بارے میں اسلامی نظریات کی توضیح وتفسیر ہے جو خاص اصولوں پر قائم ہے ، اور اسلامی حکومت کے سیاسی افکار بھی انہیں اصولوں کی بنیاد پرقابل وضاحت ہیں ۔
.۲اسلام اور اس کا سیاسی نظریہ
جس وقت ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اسلام ”سیاست اور حکومت“ کے سلسلہ میں ایک خاص نظریہ رکھتا ہے ، جواسلامی اصول و ضوابط پر مبتنی ہے توسب سے پہلے یہ سوال ہوتاہے کہ کیا دین سیاست و حکومت کے بارے میں کوئی خاص نظریہ رکھتا ہے تاکہ اسلام اس سیاسی نظریہ کو بیان کرے ؟ یہ ایک ایسا مشہور سوال ہے جو صدیوں سے مختلف ممالک اور مختلف معاشرہ میں ہوتا آیا ہے ، ہمارے ملک میں بھی یہ سوال مورد بحث چلا آیا ہے خصوصا مشروطیت کے زمانے سے آج تک اس سوال پر کافی زور دیا گیا ہے ،اور اس سلسلہ میں مختلف طریقوں سے بحث بھی ہوچکی ہے ،البتہ امام خمینی کے بیانات کے پیش نظر اور مرحوم شھید مدرس کے مشہور و معروف جملہ کہ ”ہمارا دین عین سیاست اور ہماری سیاست عین دین ہے“ جس نے ہمارے ذہن میں نقش بنا لیا ہے ، اور یہ مسئلہ ہم لوگوں کے لئے واضح اور روشن ہوچکا ہے، اور ہم اپنے لئے اس سوال کا واضح جواب رکھتے ہیں ، لیکن اسلام کے سیاسی نظریہ اور دین کی سیاست میں دخالت جیسے مسائل پر تحقیق اور بررسی کی ضرورت ہے ۔
مغربی تمدن میں دین کو جامعیت نہیں دی گئی ہے اور اس کو محدود کرکے پیش کیا گیا ہے کہ دین کا تعلق اجتماعی وسیاسی مسائل سے نہیں ہے ، فقط دین کے اندر انسان کا خدا سے رابطہ ہونا چاہئے اور فرد کا رابطہ خدا سے کیا ہے اس اس چیز کو دین کے اندر مغربی تمدن کے نزدیک بیان کیا جاتا ہے، لھٰذا سیاسی، اجتماعی ، بین الاقوامی، حکومت اور لوگوں کے درمیان روابط اور حکومتوں کے آپسی روابط یہ سب انسان اور خدا کے رابطہ سے جداگانہ چیزیں ہیں ، یعنی ان کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے دین ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے فردی مسائل اجتماعی مسائل شامل ہیں اور اس کے اندر انسان کا خدا سے رابطہ اور انسان کا آپس میں رابطہ اور دیگر سیاسی، اجتماعی اور بین الاقوامی روابط بھی شامل ہیں یعنی دین کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں ، کیونکہ اسلام کے اعتبار سے خداوندعالم تمام دنیا پر حاکم ہے لھٰذا سیاست، اقتصاد (معاش) تعلیم وتربیت، مدیریت ارو وہ تمام مسائل جو انسانی زندگی سے متعلق ہیں وہ سب دینی احکام میں شامل ہیں ۔
۳۔اسلامی سیاسی نظریہ کا بنیادی ہونا
اب جبکہ ہم نے قبول کرلیا کہ اسلام حکومت اور سیاست کے سلسلے میں اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے ، اور حکومت و سیاست کے بارے میں اسلام کی طرف ایک خاص نظریہ کی نسبت دی جاسکتی ہے ،اس نظریہ کی ماہیت و کیفیت کے بارے میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں ۔
کیا اسلام کا سیاسی نظریہ ایک بنیادی نظریہ ہے یا کسی نظریہ کی تقلید ہے ؟یعنی کیا اسلام نے یہ نظریہ اختراع اور ایجاد کیا ہے اور خدا کے نازل شدہ تمام احکام تعبدی کی طرح اس نظریہ کو پیش کیا ہے یا یہ کہ اسلام نے کسی ایک نظریہ کو لے کر اس کی تائید کرکے پیش کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت سے مسائل میں سیرت عقلاء کی تائید کی ہے ، جسے اصطلاحاً اسلام میں ”امضاء روش عقلاء“ کھا جاتا ہے، مثال کے طور پر عام انسان جس طرح کے معاملات کرتے ہیں مثلا خرید وفروخت ،کرایہ ،بیمہ وغیرہ ان کو سیرت عقلائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ، کہ لوگوں نے ان کو ایجاد کیا ہے اور شارع مقدس نے ان کی تائید فرمائی ہے ۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت ا ور سیاست کے سلسلہ میں اسلام کا نظریہ اسی طرح ہے کہ عقلاء نے کچھ حکومت و سیاست کے بارے میں نظریہ قائم کیئے اور ان کو قبول کیا ، اور شارع مقدس نے بھی ان نظریات کی تائید کرنے کے بعد قبول کرلیا ہے؟ یا یہ کہ خود اسلام نے اس سلسلے میں اپنا ایک خاص اور اختراعی نظریہ پیش کیا ہے ؟ اور دنیا کے تمام نظریات کے مقابلے میں ا سلامی حکومت کے بارے میں پیش کیا ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے حکومت اور سیاست کے بارے میں سیاسی و اجتماعی زندگی کے لئے بنیادی و اختراعی اصولوں پر مشتمل ایک مجموعہ پیش کیاہے ، نہ یہ کہ اسلام کے نظریات تقلید ی اور تائیدی ہیں جو حضرات حکومت کے مختلف اشکالات اور سیاسی فلسفہ سے آگاہی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف نظریات موجود ہیں جن میں سے ایک نظریہ ” تئوکراسی“ (الہی حکومت ) بھی ہے یہ نظریہ عیسوی صدی کے وسط میں یعنی تقریباً ایک ھزار سال پہلے یورپ میں کلیسا (عیسائی کی عبادتگاہ) کی طرف سے پیش کیا گیا مخصوصاً کیتھولک عیسائیوں کے کلیسا کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ خدا کی طرف سے لوگوں پر حاکم ہیں ، اس کے مقابلہ میں عیسائیوں کا دوسرا فرقہ یہ کھتا ہے تھا کہ حضرت عیسی مسیح (ع) کا دین سیاست سے جدا ہے ، یعنی دین اور سیاست میں کوئی ربط نہیں ہے۔
بہر حال دوسرے فرقے کا اعتقاد یہ تھا کہ پاپ کو حکومت کا حق ہے، اور خدا کی طرف سے کلیسا کو ایسا صاحب اقتدار ہونا چاہئے جو لوگوں پر خدا کی طرف سے حکومت کر سکے ، اور لوگوں کو بھی خدا کے حکم سے پاپ کی اطاعت کرنا چاہئے اس نظریہ کو تئو لوکراسی حکومت نام دیا گیا ۔
جب یہ کھاجاتا ہے کہ اسلام عام لوگوں کی ایجاد شدہ حکومت کے علاوہ اپنے خاص نظریہ کے تحت اسلامی اور الہی حکومت کوپیش کرتاہے تو کیا اس سے یھی تئوکراسی حکومت مراد ہوتی ہے جسے مغرب اور یورپ میں سمجہا جاتاہے اور الٰھی حکومت ان کے تمدن میں اسی معنی میں پہچانی جاتی ہے ؟ اور جس طرح تئوکراسی حکومت میں خدا وند عالم نے حاکم کو وسیع پیمانے پر اختیار ات دیئے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں پر حکومت کرسکتا ہے اور لوگوں پربھی واجب ہے کہ اس حاکم کی مرضی کے مطابق عمل کریں ؟کیا حکومت الہی و ولایی کے مطابق بھی جس کا ہم دعوی کرتے ہیں اور اسلام کے ولایت فقیہ کے نظریہ کے تحت کیا ولی فقیہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں پر حکومت کا حق رکھتا ہے اور کیا اس کو یہ بھی حق ہے کہ جس طرح وہ چاہے قوانین بنا کر ان کے ذریعہ لوگوں پر حکومت کرے ، اور لوگوں پر بھی اس کی اطاعت واجب ہے ؟
یہ سوال بہت اہم ہے اور ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ایک مناسب بحث اور تحلیل کی ضرورت ہے تاکہ اس سلسلہ میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ دور ہوجائے ۔
مذکورہ سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس الھی حکومت کے ہم معتقد ہیں اور وہ تئوکراسی حکومت (جو مغرب اور یورپ میں معروف ہے ) زمین تا آسمان فرق رکھتی ہے ، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہئے کہ الھی حکومت اسلام کی نظرمیں وہی حکومت ہے کہ جس کے عیسائی خصوصا ًفرقہ کیتھولک خدا اور پاپ بارے میں قائل ہیں ۔
سیاسی صاحب نظرافراد نے حکومت کے نظریات کی کثرت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے :
(۱) ڈکٹیٹری حکومت(شہنشاہی حکومت)
(۲)ڈیموکراٹک (جمہوری حکومت) اگرچہ ان دونوں کی بہت سی قسمیں موجود ہیں لیکن کلی طور پر حکومت کی دو قسمیں ہیں ۔
پہلی قسم ایسی حکومت جس میں حاکم اپنی مرضی سے حکومت کرتا ہے اور خود فرمان جاری کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے اپنی حکومت کو چلاتا ہے اور اپنی فوجی طاقت کے ذریعہ لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرتا ہے ۔
دوسری قسم ایسی حکومت جس میں لوگوں کی رائے دخالت رکھتی ہے اور لوگ اپنی مرضی سے اپنے حاکم کو چنتے ہیں اور حاکم بھی لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں یعنی ان کی حکومت لوگوں کے ارادے اور ان کی چاہت پر موقوف ہوتی ہے۔
۴۔اسلامی حکومت کی حقیقت اور اس کے ارکان
جن لوگوں نے حکومت کے سلسلہ میں مغربی تقسیم کو قبول کیا ہے اور معتقد ہیں کہ حکومت دو حال سے خالی نہیں ہے حکومت یا ڈکٹیٹری ہے یا ڈیموکراٹک اور جمہوریت ، اب یھاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت ڈکٹیٹری حکومت ہے یعنی جو بھی حکومت پر ہو مختار ہے مثلا ًہمارے زمانہ میں ولی فقیہ اپنی طاقت و قدرت اور اسلحہ کے ذریعہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے یا اسلامی حکومت کا کوئی نیا اندازھے ؟ یا اسلامی حکومت کی کوئی تیسری شکل ہے کہ نہ ڈکٹیٹری ہے اور نہ جمہوریت ؟
بہر حال حکومت کی دوگانہ تقسیم ایسی ہیں جن کو تمام لوگوں نے قبول کیا ہے لھٰذا اسلامی حکومت مذکورہ تقسیم سے خارج نہیں ہے یا یہ حکومت ڈکٹیٹری ہے یا جمہوری اگر اسلامی حکومت جمہوری ہے تو اسلامی حکومت کو یورپی حکومت میں پائے جانے والے طور طریقے اپنانا چاہئیں ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسلامی حکومت ڈکٹیٹری حکومت ہوگی جو صرف خاص فرد کی مرضی پر تکیہ زن ہوتی ہے اور اس سلسلہ میں تیسر ے نظریہ کو انتخاب کرنے کی ضرورت نھیں ھے،لھٰذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس اہم سوال کا جواب دیں اور بیان کریں کہ اسلامی حکومت ڈکٹیٹری ہے یا جمہوری یا کوئی تیسری قسم انہیں سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتاہے کہ اسلامی حکومت کے مقدمات اور اس کے ارکان کیا ہیں ؟ وہ کون سے ارکان ہیں کہ جن پر حکومت اسلامی کو توجہ رکھنی چاہئے تاکہ واقعی طور پر حکومت اسلامی ہوسکے ؟ جو حضرات ہمارے مذہب اور فقہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر نماز کے ارکان میں کوئی ایک بھی رکن چھوٹ جائے چاہے عمداًطور پر چھوڑا جائے یا سھواً چھوٹ جائے اس کی نماز باطل ہوجائیگی در حقیقت ارکان نماز سے ہی نماز ہے اسی طرح اسلامی حکومت کے ارکان ہونا چاہئیے کہ اگر وہ ارکان موجود ہوں تو اس حکومت کو اسلامی حکومت کھا جائے گا اوراگر وہ ارکان نہیں ہیں یا اگر ان میں خلل (کمی و زیادتی ) پائی جائے تو اس کو حکومت اسلامی نہیں کھا جائے گا ۔
انہیں ارکان کی اہمیت کے پیش نظر جن پر اسلامی حکومت موقوف ہوتی ہے، ہم ان ارکان سے آگاہ ہونے کی خاطر ان کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں ، کیونکہ جب ہم ان ارکان کو پہچان لیں گے تو اسلامی حکومت کا معیار و ملاک ہمارے ھاتہ میں آجائے گا کہ جس کے ذریعہ سے ہم اسلامی اور غیر اسلامی حکومت کے فرق کو مکمل طریقہ سے پہچان لیں گے اسی وجہ سے اس اہم سوال کا جواب بہت ضروری ہے ۔
۵۔اسلامی حکومت کا ڈھانچہ ، اس کے اختیارات اور وظایف کی وسعت
اس سلسلہ کا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے حکومتِ اسلامی کی ایک خاص شکل وصورت معین کی ہے؟ جیساکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی اس دنیا میں حکومت کے کیا ڈھانچے اور طور طریقے ہیں اور قدیم زمانے میں بھی حکومت کی شکل وصورت ہوتی تھی جو اس وقت نہیں ہے۔
موجودہ حکومتوں کی بعض قسمیں اس طرح ہیں :
۱۔بادشاہی حکومت،مشروطہ ومطلق۔
۲۔ جمہوری حکومت (ریاستی یا پارلیمینٹ کی حکومت)۔
۳۔ الہی حکومت۔
کیا اسلام نے حکومت کی ان شکلوں میں سے کسی ایک کو قبول کیا ہے یا اسلام نے خود ایک خاص شکل معین کی ہے جو مذکورہ شکلوں سے فرق رکھتی ہے یا یہ کہ اسلام نے حکومت کے لئے کو ئی خاص طریقہ کو نہیں اپنایا ، اور فقط حکومت کے لئے چند معیار معین کئے ہیں جن کا ہر طرح کی حکومت میں لحاظ کرنا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اسلام کا حکم ہے کہ حکومت میں عدالت کا لحاظ رکھا جائے لیکن عدالت کا کس طرح لحاظ رکھا جائے؟ کیا عدالت زمان ومکان کے اعتبار سے لحاظ کی جائے؟ چنانچہ دنیا کے کسی بھی گوشہ میں کسی بھی وقت زمان ومکان کے اعتبار سے اس طرح کی عدالت لحاظ کیا جاسکتا اور اسلام نے ایک خاص شکل وصورت کی عدالت برتنے پر اصرار نہیں کیا ہے؟! اور اسلام کی نظر میں حکومت کی مناسب شکل اس کے معیار کی رعایت پر ہے ۔
اور اگر اسلام نے حکومت کے لئے کسی خاص شکل وصورت کا انتخاب کیا ہے تو کیا اسلام کی نظر میں اس حکومت کا ڈھانچہ ایک ثابت اور پائیدار ڈھانچہ ہے ؟ یا یہ کہ اس کا ڈھانچہ غیر پائیدار ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر تبدیلی و تغیر ہوسکتی ہے ؟
اس طرح کے سوالات اسلامی حکومت کے ڈھانچے اور شکل وصورت کے بازے میں ہوتے رہتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کے جوابات بھی دئے جائیں ۔ فلسفہ حکومت کے سلسلے میں ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حاکم اور رئیس چاہے وہ کوئی ایک فرد ہو یا ایک گروہ یا ایک مجلس وانجمن کی شکل میں ہو، یعنی اسلامی حکومت کے اختیارات کیا کیا ہیں ؟ اور اسی طرح حکومت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ؟ کیو نکہ گذشتہ زمانے اور عصر حاضر کی حکومتوں میں ذمہ داریوں کے لحاظ سے کافی فرق نظر آتا ہے بعض حکومتیں اختیارات اور وظایف کے لحاظ سے کافی محدود ہوتی ہیں مثلا ًیہ کہ بعض حکومتیں فقط لوگوں کی عام حفاظت کی ذمہ دارہوتی ہیں جو اہم ہوتے ہیں ، اور اکثر کاموں میں خود لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بعض حکومتوں کے اختیارات بہت وسیع ہوتے ہیں جس کے نتیجہ میں اس کے وظایف اور ذمہ داریاں بھی وسیع ہوتی ہیں اس حکومت کی ذمہ داریاں بہت مہم اور خطر ناک ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اسے جواب دہ ہونا ہوتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو تمام لوگوں پر نہیں چھوڑا جاسکتا کیونکہ لوگوں کو حق ہے کہ وہ حکومت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں مطالبہ کریں ۔
اسی طرح یہ بھی روشن ہونا چاہیے کہ اسلام کے سیاسی فلسفہ کے تحت اسلامی حکومت نے کیا کیا اختیارات و ذمہ داریاں معین کی ہیں اور بلا شبہ یہ اختیارات و ذمہ داریاں مناسب اور متعادل ہونی چاہئیں ، جن مقدمات پر کوئی کام موقوف ہو ان مقدمات کو فراہم نہ کرکے کسی کے سپرد کوئی ذمہ داری کی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے ۔
بہر حال اسلامی حکومت کے اختیارات اور اس کی ذمہ داریاں کیاکیا ہیں ؟ اس اہم سوال کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔
۶۔اسلامی حکومت میں لوگوں کا کردار اور چند دیگر سوالات
آج کے انہیں اہم سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ حکومت اسلامی میں لوگوں کا کردار کیا ہے ؟ لوگوں کے اختیارات اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ؟انہیں سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ صدر اسلام میں حضرت رسول خدا ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی حکومتوں کی کیاشکل تھیں ؟ اسی طرح بنی امیہ و بنی عباس وغیرہ کی حکومتیں کس حد تک اسلامی تھیں ؟
اور جس وقت ہم اسلامی حکومت کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مراد مذکورہ حکومتوں سے کون سی حکومت مراد ہوتی ہے؟ اور تاریخ میں اسلامی حکومت کی تشکیل کس طرح ہوتی آئی ہے کہ نتیجةً اسلامی حکومت کی یہ شکل اسلامی انقلاب کے ذریعہ ایران میں بھی وجود میں آئی؟
البتہ مذکورہ سوالات کے ضمن میں دوسرے جزئی سوال بھی ہوتے ہیں منجملہ یہ سوال کہ کیا ہماری یہ حکومت سو فی صد اسلامی حکومت ہے؟ اور کیا اس میں اسلامی حکومت کے تمام معیار و ضوابط موجود ہیں ؟ اور اگر اس میں وہ تمام معیار وضوابط موجود ہیں تو کیا اس حکومت نے ان کی رعایت کی ہے؟ اسی طرح یہ سوال کہ اس حکومت میں کیا کیا نقص ہیں ؟
۷۔ اسلام کے سیاسی نظریہ کو پہچاننے کے طریقے
قبل اس کے کہ ہم مذکورہ سوالات اور شبھات کا جواب دیں اور فلسفہ سیاسی اسلام میں وارد ہوں اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس روش وطریقے کو پہلے بیان کردیں جس کو مذکورہ بحث کی تحقیق اور بر رسی میں اپنائیں گے اس بحث کی متدلوژی (طوروطریقہ) کیا ہے ، بہر حال یہ ایک مقدماتی بحث ہے کہ جس کو شروع میں بیان کردینا چاہئے، کیا یہ ہماری بحث کا طریقہ اور عقلی روش ہے؟یعنی کیا ہم عقلی دلیلوں کے ذریعہ اسلام کے نظریات کو بیان کریں گے ؟ یا ہماری روش اور شیوہ بحث تعبدی اور نقلی ہوگا یعنی قرآن وسنت کے تابع ہے؟ گویا اس حکومت کے اصول وضوابط قرآن وروایات سے اخذ کئیے جائیں گے؟
یا یہ کہ اسلامی سیاست ایک تجربہ کی طرح ہے؟ کہ جس کے درست اور غیر درست ہونے کو تجربہ ہی ثابت کرسکتا ہے؟ اس صورت میں ہماری گفتگو کا شیوہ تجربہ ہوگا اور فیصلہ کرنے کا معیار بھی تجربہ ہوگا ۔
بہر حال چونکہ ہماری بحث عقلانی پہلو رکھتی ہے اسی وجہ سے اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ عقلی بحث کی کم از کم دو قسمیں ہیں :
(۱) جَدَلی طریقہ ۔
(۲) برہانی اور دلائل کا طریقہ ۔
جس وقت ہم کسی گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور عقلی لحاظ سے کسی ایک موضوع کی تحقیق کرتے ہیں تو کبھی ایسے اصول ومقدمات سے بحث کرکے مجھول نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ جن مقدمات اور اصول کوہم اور ہمارا مخالف قبول کرتا ہے اس کے مقابلہ میں وہ برہانی راہ وروش ہے کہ جس میں تمام مقدمات بھی مورد بحث قرار پاتے ہیں گویا بحث خودقضایا اولیہ ویقینیات وبدیھیات سے ہوتی ہے تاکہ ان کے ذریعہ ہمارا استدلال اور برہان یقینی اور قطعی قرار پائے، اور ظاہر ہے اگر ہم اس راستہ کو اختیار کریں تو بحث طولانی ہوجائے گی۔
مثال کے طور پر اگر ہم برہان کے ذریعہ ثابت کرنا چاہیں کہ حکومت اسلامی میں عدل وانصاف رعایت ہونا چاہئے تو سب سے پہلے ہمیں عدل کے مفہوم اور معنی کو واضح کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دیں کہ عدالت کا کس طرح لحاظ رکھا جائے؟ اسی طرح یہ سوال کہ عدالت اور آزادی ایک جگہ جمع ہوسکتی ہیں یا نہیں نیز اسی طرح یہ سوال کہ عدالت کے معیار کو کون معین کرے؟کیا عدالت کے معیار کو خدا وندعالم معین کرے یا عقل؟
مذکورہ سوالات کے حل ہونے کے بعد یہ سوال ہوتاہے کہ اس سلسلہ میں عقل کس حد تک فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے؟ کیا عقل کی قضاوت ایک خاص مقدار میں ہے یا مطلق طور پر اس طرح یہ بحث طول پکڑجاتی ہے یھاں تک کہ اصول اولیہ اور مسائل معرفت شناسی کے بارے میں مورد سوال قرار پاتے ہیں بہرحال ان کو بھی واضح وروشن ہونا چاہئیے، خلاصہ یہ عقل کیا ہے؟ اور اس کی دلالت کس طرح کی ہے؟ عقل کس طرح استدلال کرتی ہے؟ اور عقل کا اعتبار اور اس کا حکم کس حد تک قابل قبول ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم اس طرح کے مسائل پر تحقیق کریں تو مختلف علوم سے بحث کرنی پڑے گی ، جو ایک طولانی مدت چاہتی ہے جو مفقود ہے۔
بہر حال برہانی بحث کرنا اپنی جگہ مقدس اور محترم ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ برہانی و استدلالی بحث کرنے کے لئے بہت سے علوم کا سھارا لینا پڑتا ہے اور بہت کم افراد ہی ان علوم میں مھارت رکھتے ہیں اور علم کے ماہر انسان اس کے محدود مسائل تک ہی رسائی رکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ کام کافی مشکل ہے اور اس طرح کے مسائل کو واقعاً حل کرنے ایک طویل مدت درکار ہے ہم بھی اپنی گفتگو میں اگر اسی برہانی راستہ کو اپنائیں اور الگ الگ مسائل سے بحث کرکے بدیھی اصول اور مبنا تک پہنچیں تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے،لھٰذا اپنی بحث کو منزل مقصود تک نہیں پہچا سکتے، اسی وجہ سے جہاں برہانی بحث سادہ اور غیر پیچیدہ ہے وہاں برہانی اور استدلالی بحث کریں گے اور اس کے علاوہ تمام موارد میں جدلی بحث کریں گے کیونکہ جدلی بحث کا مناسب ترین طریقہ ہے۔
در حقیقت یہ ہدف اور نتیجہ تک پہنچنے کے لئے یہ راستہ درمیانی راستہ ہے ،یعنی یہ راستہ دوسروں کو قانع کرنے کے لئے عام راستہ ہے ، خداوند عالم نے قرآن مجید میں بارہا دشمن کو قانع کرنے کے لئے اور اپنی طرف سے اتمام حجت کے لئے اس کو بیان کیا ہے ، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم بھی اس راستہ کو اپنائیں او ردوسروں سے اسی کے ذریعہ بحث اور گفتگوکریں ،ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے :
(
ا دْعُ إِلیٰ سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهمْ بِالَّتِی هیَ ا حْسَن
)
”حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث وجدل کرو۔“
حوالہ
 0%
0%
 مؤلف: آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی دام ظلہ
مؤلف: آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی دام ظلہ