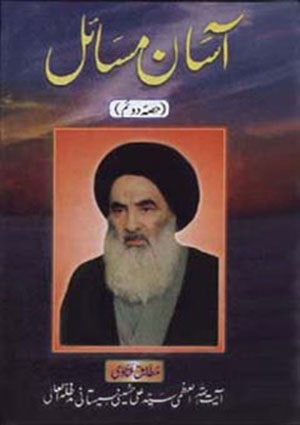زکوٰۃکے بارے میں گفتگو
زکوٰۃ ان پانچ رکنوں میں سے ایک رکن ہے کہ جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے میرے والد نے فرمایا:
زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے حدیث میں اس کے متعلق وارد ہوا ہےکہ۔
”ان الصلوة لاتقبل من مانع الزکوٰة‘
جو زکوٰۃنہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔
میرے والد نے اتنا بیان کرنے کے بعدمزید فرمایا جب زکوٰۃکے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔
بسم الله الرحمن الرحیم
(
خذ من اموالهم صدقه تطهر هم وتز کیهم بها
)
ان کے اموال کا صدقہ لے کر اس کے ذریعہ ان کو پاک اور ان کا تزکیہ کرو۔
تو رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم
نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں جاکرندا کرے کہ۔
”ان الله تبارک وتعالی قد فرض علیکم الزکوٰة کما فرض علیکم الصلوة“
اللہ تعالٰی نے تم پر زکوٰة کو اسی طرح واجب کیا ہے جس طرح نماز واجب کی ہے۔
اور جب سال کا پہلا دن آیا تو آپ نے منادی کو حکم دیا جاکر لوگوں میں منادی کروکہ:
”ایها المسلمون زکوااموالکم تقبل صلاتکم
“
”اے مسلمانو:اپنے اموال کی زکوٰۃ دو،ناکہ تمہاری نماز قبول ہو“
پھر آپ نے صدقہ وصول کرنے والوں سے کہا کہ وہ لوگوں سے جاکر زکوٰۃ لیں۔
میری والد نے فرمایا: ایک روز رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
مسجد میں پہونچ کر یہ فرمایا: اے فلاں! کھڑے ہوجاؤ،اے فلاں !کھڑے ہوجاؤ،اے فلاں! کھڑے ہو جاؤ،اے فلاں! کھڑے ہوجاؤ،یہاں تک کہ آپؐ نے پانچ آدمیوں کو مسجد سے نکالتےہوئے دیا اور فرمایا: تم ہماری مسجد سے نکل جاؤ ،جب تم زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس میں نماز نہ پڑھو‘اسی کے ساتھ آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث مجھ سے بیان کی اس وقت آپ کے چہرہ پر حزن ملال کے بادل چھاگئے تھے،اس حدیث میں ہے :
”ان الله عزو جل یبعث یوم القیامةناسامن قبور هم مشدودة ایدیهم الی اعناقهم الخ
“
فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل روز قیامت کچھ لوگوں کو ان کی قبروں سے محشور کرے گا،ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے ایسے بندھے ہوں گے کہ وہ انگلی کے ایک پور کو بھی اس سے جدا نہیں کرسکتے‘اور فرشتے ان کو سختی کے ساتھ ہانک رہے ہونگے اور آواز دے رہے ہونگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے خیر قلیل کے ذریعہ خیر کثیر کو روکا،یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے(مال کثیر عنایت کیا اور انہوں نے اپنے اموال میں سے حق اللہ( زکوٰۃ) کو ادا نہیں کیا۔
میرے والد نے فرمایا: قرآن مجید میں بہت سی آیات کریمہ میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جس سے شریعت اسلامی میں زکوٰة کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔
سوال: میں نے اپنے والد سے زکوٰۃکے بارے میں معلوم کیا (کہ زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟)
تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے ذریعہ اس کا جواب مجھے دیا، اس حدیث میں آپ نے فرمایا:
”انما وصفت الزکاة اختباراً اللاغنیاء ومعونة للفقراء ولو ان الناس ادوازکاة اموالهم مابقی مسلم فقیر امحتاجا
“
زکوٰۃ اغنیاء( مالداورں)کے لئے آزمائش ہے اور فقراء (غربیوں)کے لئے ایک مدد ہے اگر لوگ اپنے اموال سے زکوٰۃادا کریں تو کوئی بھی مسلمان غریب محتاج نہ رہے اوراس سےمستغنی ہوجائے جو اللہ نے اس کے لئے فرض کیا ہے اور لوگ ضرور ت مند اور حاجب مندنہ رہیں اور نہ بھوکے وننگے رہیں لیکن اگر ایسا ہے تو یہ صرف مالدار کے گناہوں کی بناپر ہے اور اللہ تعالیٰ کو حق پہونچتا ہے کہ وہ ان کو رحمت سے دور رکھے کہ جنھوں نے اپنے مال سے حق خدا کو ادانہ کیا۔
میں نے سوال کیاکہ کیا ہر مال میں زکوٰۃواجب ہے؟
تو انھوں نے جواب میں فرمایا مندرجہ ذیل بیان کی ہوئی چیزوں میں زکوٰۃواجب ہے۔
پہلی
سونے/ چاندی کے سکوں میں چند شرطوں کے ساتھ۔
دوسرے
گہیوں /جو / کھجور/ کشمش ان میں بھی چند شرائط ہیں۔
تیسرے
اونٹ،گائے،بھینس،بھیڑ،بکری ،دنبہ،ان میں بھی کچھ شرطیں ہیں۔
چوتھے
تجارتی مال میں اس میں بھی کچھ شرائط ہیں۔
سوال: وہ کونسی واجب شرطیں ہیں جو سونے چاندی کے سکوں میں پائی جاتی ہیں کہ جن کی طر ف آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا؟
جواب: چند شرائط ہیں۔
۱ سونے کی مقدار عرفاً ۱۵ / مثقال ہوجائے تو اس کی زکوٰۃ، اس کا چالیسواں حصہ ہوگی،اور جس وقت اس پر تین مثقال کا اضافہ ہو تو اس کی زکوٰة چالیسواں حصہ ہوگی ۔
(یعنی پندرہ مثقال کے بعد جب بھی تین مثقال کا اضافہ ہوگا اس کے چالیسواں حصہ سے زکوٰۃ واجب ہے،تین سے کم اور زیادہ پر زکوٰۃنہیں ہے)لیکن چاندی کی مقدار عرفاً ایک سوپانچ ۱۰۵ مثقال ہوجائے تو اس کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہوگی اور جب بھی ۲۱/ مثقال کا اضافہ ہو تو اس پر چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہوگا۔
سوال: میں نے کہا اگر سونے چاندی کے سکوں کی مقدار اس حد سے کم ہو تو؟
جواب: تو اس پر زکوٰة واجب نہیں ہے ۔
۲ سونے چاندی کے ایسے سکے ہوں، جو اس زمانہ کے خریدو فروخت (معاملات ) میں عملاً رائج ہوں۔
۳ گیارہ مہینے پورے گزرنے کے بعد بارہو یں مہینے میں داخل ہوجائے اور وہ مالک کی ملکیت میں رہے۔
سوال: کیا سونے کے کڑے اور سونے چاندی کے زیورات اور سونے چاندی کے دوسرے ٹکڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟
جواب: ان پر واجب ہے۔
۴ پورے سال مالک کے تصرف میں رہیں ہوں پس جو مال عرفاً کچھ مدّت کے لئے ضائع ہوجائے تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔
۵ مالک بلوغ اور عقل کے اعتبار سے کامل ہو،لہٰذابچےاورمجنون کےاموال میں زکوٰۃواجب نہیں ہے۔
دوسرے
جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ گیہوں،جو، کھجور،کشمش ہے،اور جب ان کی مقدار ان کے سوکھنے کے بعد تین سوصاع کو پہونچ جائے تو اس وقت ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور یہ تقریباً( ۸۴۷) کلو گرام کے قریب ہے جیسا کہ منقول ہے،اوران میں زکوٰۃ کی واجب مقدار نیچے بیان کی جارہی ہے۔
۱ کھیتی اگر بارش کے پانی یا نہر کے پانی سے ان دونوں کے مشابہ کسی ایسی چیزسے سینچائی کی گئی ہو جس میں کھیتی کی سینچائی کے لئے محنت ومشقت کی ضرورت نہ پڑے تو ایسی صورت میں ان کی زکوٰۃ دسواں حصہ ہوگی ۔
ب اور اگر سینچائی ہاتھ یا کسی آلہ کے ذریعہ مثلا ٹیوب ویل وغیرہ سے ہو تو اس کی زکوٰۃ بیسواں حصہ ہوگی۔
جواب: اور جب سینچائی کبھی ہاتھ یا کسی دوسرے آلہ کے ذریعہ اور کبھی بارش کے ذریعہ ہو، توپھر اس کی زکوٰۃ آدھی کھیتی کی بیسواں حصہ اور آدھی کی دسواں حصہ (یعنی ۳/۴۰) حصہ دی جائے گی۔
مگر یہ کہ ان دونوں سینچائیوں میں سے ایک بہت کم ہو اور ایک بہت زیادہ ہو،تو پھر زیادہ والی سنچائی کی نسبت زکوٰۃ نکالی جائے گی۔
سوال: جب مقررہ نصاب سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے ؟
جواب: اور کیایہاں دوسرے بھی شرائط ہیں۔
سوال: ہاں زکوٰۃواجب ہونے کے وقت محصول مالک کی ملکیت میں ہو،اگر زکوۃ واجب ہونے کے بعد وہ مالک ہواہو تو پھر زکوة واجب نہیں ہے۔
سوال: زکوٰۃ کا تعلق ان چار محصول پر کب ہوگا؟
جواب: ان سے زکوٰۃ کا تعلق اس وقت ہوگا جب کہ گیہوں کا نام،جو کانام،یا کھجور(خرما)کا نام، یا کشمش کانام ان پر صادق آئے (یعنی جب ان چیزوں کو ان کے نام سےموسوم کیا جائے)
تیسرے
جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ بھیڑ/بکری / اونٹ گائے اور بھینس ہے ان کی زکوٰۃ میں چند چیزیں شرط ہیں:
ان کی تعداد کا حدنصاب تک پہونچنا،اور وہ ان کی معین تعداد ہےجس پر زکوٰۃ واجب ہے پس اونٹ جب پانچ تک پہنچ جائے تو ان پر ایک بکری کی زکوٰۃ دینا واجب ہے اور جب دس ہوجائے تو دوبکریاں اور جب پندرہ ہوجائے تو تین بکریاں اور جب بیس ہوجائے توچاربکریاں اور جب پچیس( ۲۵) تک پہونچ جائے تو زکوٰۃایک ایسی اونٹنی ہے کہ جو اپنی عمر کے دوسرے سال میں داخل ہوچکی ہو،اور جب چھتیس ( ۳۶) اونٹوں تک پہنچ جائے تو ان کی زکوٰۃ ایک ایسی اونٹنی ہےجو ا پنی عمر کے تیسرے سال میں داخل ہوچکی ہو،اس کے علاوہ اونٹ کے اور بھی نصاب ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں جگہ نہیں ہے۔
اور بھیڑ بکری میں جبکہ ان کی تعداد چالیس ( ۴۰) تک پہونچ جائے تو ان کی زکوٰۃ ایک بکری اور جب ایک سوا کیس ( ۱۲۱) تک ان کی تعداد پہونچ جائے تو دوبکریاں اور جب دوسوایک ( ۲۰۱) تک پہونچ جائے تو چار بکریاں اور جب ان کی تعداد چار سویا اس سے زیادہ ہو جائے تو ان میں سے ہر سوپر ایک بکری دی جائے گی،اسی طرح جیسے جیسے ان کا عدد بڑھتا جائے گا ویسے ہی ویسےہر سوپر ایک بکری دی جائے گی۔
گائے اور بھینس میں جب ان کی تعداد تیس تک پہونچ جائے تو ان کی زکوٰۃ ایک ایسا گا ئے کا بچہ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہوچکا ہو ،اور اگر ان کی تعداد چالیس تک پہونچ جائے تو ان کی زکواۃ ایک ایسی گا ئے کابچہ مادہ ہے جو اپنی عمر کے تیسرے سال میں داخل ہوچکی ہو، اس اعتبارسے گائے ہویا بھینس کوئی فرق نہیں ہے۔
اوردو نصاب کے درمیان یا محدود مقدار میں اونٹ اور گائے اور بھیڑ بکری پر زکوٰة نہیں ہے اس بنا پر اگر نصاب سے زیادہ ان کی تعداد بڑھ جائے تو جب تک ان کی تعداد کسی نصاب تک نہ پہونچ جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ۔
۲ حیوانات(پورےسال)ایسی زمین میں چریں جس کا خدا کے علاوہ کوئی مالک نہ ہو لیکن اگر اس کے مالک نے ان کو گھانس یا چارہ چاہے سال کے کچھ ہی دنوں میں دیاہوتوان پر زکوة واجب نہیں ہے۔
اور حیوانات میں ان سے کام لینا معتبر نہیں کہ جن حیوانات سے کام لیا جاتاہوان پر زکوٰۃ نہ ہو پس اگر ان سےسنیچائی جو تائی وغیرہ میں کام لیاجاتاہو تب بھی ان پرزکوٰةواجب ہے۔
۳ وہ تمام سال مالک کی یامالک کے ولی کی ملکیت میں رہے ہوں پس ا گر سال میں کچھ مدت کے لئے ان کی چوری ہوجائے تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے ۔
۴ وہ حیوانات جوگیارہ مہینے گزار کربار ہویں مہینہ میں داخل ہوگئے ہوں اور وہ مالک کی ملکیت میں ہوں۔
چوتھے
جس پر زکوٰۃ واجب ہے،وہ مال و تجارت ہے اور یہ وہ مال ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے کہ وہ اس کا فائدہ تجارت کے ذریعہ اس کے معاوضہ کامالک ہوگا اس کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہوگی جبکہ تمام نیچے بیان کئے ہوئے شرائط اس میں جمع ہوں۔
( ۱) مالک بالغ وعاقل ہو ۔
۲ مال (تجارت )حد نصاب کو پہنچ جائے اور اس کا نصاب و ہی ہے جو سونے یا چاندی کے سکوں سے کسی ایک کا نصاب ہوتا ہے لہٰذا اسے سونے اور چاندی کے بیان میں ملاحظ کیجئے۔
( ۳) فائدہ اور تجارت کی نیت پر ایک سال گزرجائے۔
۴ پورے سال فائدہ حاصل کرنے کی نیت کو بدل کر اس مال کو اپنی ضرورت زندگی پر صرف کرنے کا ارادہ کرلیا تو پھر اس پر زکوٰة واجب نہیں ہے۔
۵ پورے سال مالک اوراس مال کے تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔
سوال: جب زکوٰۃ نکالی جائے تو وہ کس کو دی جائیگی؟
جواب: وہ زکوٰۃکے مستحقین کو دی جائے گی اور زکوٰۃ کےمستحقین کی چند شرطوں کے ساتھ آٹھ قسمیں ہیں خداوند متعال فرماتاہے:
(
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
صدقات صرف فقراء‘مساکین اور صدقات وصول کرنے والے اور جن کی تالیف قلب منظور ہے‘غلاموں کو آزاد کرنے میں ‘قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لئے ،اور راہ خدا میں کام کرنے کے لئے،اور مسافروں کی امداد کے لئے( صرف کی جائے) یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے(سورۂ توبہ)
سوال: فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟
جواب: فقیروہ ہے جو اپنے اور اپنے اہل وعیال کے سال بھر کا خرچ نہ رکھتا ہو،اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی صنعت وحرفت ہو جس کے ذریعہ وہ اپنا اور اپنے اہل وعیال کا خرچ حاصل کرسکے اور مسکین وہ ہے جو فقیر سے زیادہ بد حال وتنگ دست ہو۔
سوال: زکوٰۃکے وصول کرنے والے کون ہیں؟
جواب: زکوٰۃ کے وصول کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو نبیصلىاللهعليهوآلهوسلم
یا امامؑ یا حاکم شرع یا اس کا نائب زکوٰۃ کے وصول کرنے اور اس کا حساب وکتاب رکھنے اور اس کو بنی وامام وغیرہ یا مستحقین تک پہونچنے پرمقرر کریں۔
سوال: یہ مؤلفتہ القلوب کون لوگ ہیں؟
جواب: مولفتہ القلوب وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اگر کچھ مال دیا جائے تو ان کی نظر میں اسلام کی قدر و قیمت بڑھے گی یا وہ کفار کہ جن کو اگر کچھ مال دیا جائے تو اسلام کی طرف راغب ہونگے،یا مسلمانوں کی جنگ میں مدد کریں گے اور ان کی طرف سے دفاع کریں گے۔
اور اس طرف اشارہ کرنا بہتر ہوگا کہ زکوٰة کا دینے والا ان دو آخری قسموں کو خود اپنی زکوٰة دینے پر ولایت نہیں رکھتا بلکہ امام یا ان کے نائب کی نظر پر یہ بات موقوف ہے یعنی اگر وہ چاہیں تو ان دونوں کوزکوٰة دے سکتے ہیں( یعنی عاملین زکوٰۃ اور مولفتہ القلوب کو)
سوال: آیت میں وفی الر قاب آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: وفی الرقاب(سے مراد )وہ غلام جوخریدے اور آزادکئے جاتے ہیں۔
سوال: والغارمون سے کیا مرادہے؟
جواب: غارمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہیں اور وہ اپنےشرعی قرضوں کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔
سوال: اور فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟
جواب: فی سبیل اللہ سے تمام کار خیر مراد ہے مثلاً مسجدوں،پلوں وغیرہ کا بنوانا اور اس سلسلہ میں بھی حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے۔
سوال: وابن السبیل سے کیا مراد ہے؟
جواب: ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کا مال سفر میں ختم ہوگیا ہو،اور اس کے لئے سفر سے واپسی کے لئے قرض لینا بھی ممکن نہ ہو،یا اس کے لئے مشکل ہو(جیسے اس کے شہر میں اس کا مال ہو اور وہ اس کے بدلے میں یا اس کو کرایہ پر دینے سے معذور ہو) پس اس کو واپسی کا خرچ زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا بشرطیکہ اس کا یہ سفر معصیت پر مبنی نہ ہو۔
یہ زکوٰة کے اورمستحقین ہیں اس کے علاوہ شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جارہی ہے وہ مومن ہو( اور تارک صلوة نہ ہویا شراب خوارنہ ہو،یا فسق وفجور کو کھلم کھلا انجام نہ دیتا ہو) اورجس کوزکوٰۃ دی جارہی ہو وہ اس کو گناہوں میں صرف نہ کرے (بلکہ اس کو کسی ایسے کو بھی نہ دے جس کے دینے پر گناہ کرنے پر اور برے کاموں کے ہونے پر مدد ہو،چاہے وہ خود اسے گناہوں پر خرچ نہ کرے،اور یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ ایسے کو نہ دی جائے کہ جس کا نان ونفقہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہو جیسے بیوی اورمستحق ہاشمی(سید) کیونکہ ہاشمی (سید)کو صرف ہاشمی کی زکوٰة لے سکتا ہے(غیرسید کی نہیں )
 0%
0%
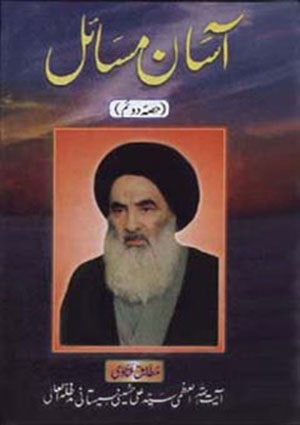 مؤلف: آیت اللہ العظميٰ سید علی سیستانی مدظلہ العالی
مؤلف: آیت اللہ العظميٰ سید علی سیستانی مدظلہ العالی