خواہشیں ! احادیث اہل بیت کی روشنی میں
 0%
0%
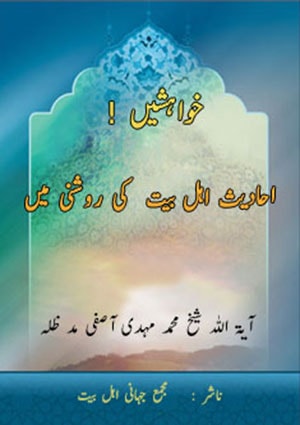 مؤلف: آیت اللہ محمد مہدی آصفی
مؤلف: آیت اللہ محمد مہدی آصفی
: مصنف/ مؤلف
: مصنف/ مؤلف
زمرہ جات: اخلاقی کتابیں
صفحے: 349
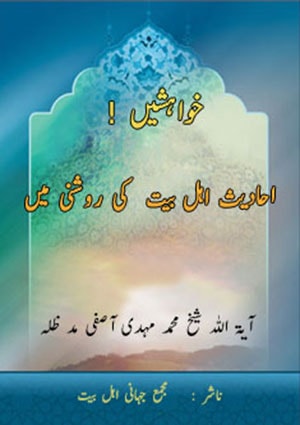
مؤلف: آیت اللہ محمد مہدی آصفی
: مصنف/ مؤلف
: مصنف/ مؤلف
زمرہ جات:
مشاہدے: 109517
ڈاؤنلوڈ: 4807
تبصرے:
- حرف اول
- مقدمہ ٔ مؤلف
- حدیث قدسی
- حدیث قدسی
- پہلی فصل
- ''ہویٰ'' (خواہش)قرآن وحدیث
- کی روشنی میں
- بنیادی محرکات
- 1۔فطرت
- 2۔عقل
- 3۔ارادہ
- 4۔ضمیر
- 5۔قلب ،صدر،
- 6۔ہویٰ(خواہشیں)
- ''ہویٰ'' کی اصطلاحی تعریف
- ''ہویٰ''کے خصوصیات
- 1۔چاہت میںشدت
- 2۔خواہشات میں تحرک کی قوّت
- 3۔خواہشات اور لالچ کی بیماری
- خواہشات پر عقل کی حکومت
- انسان ،عقل اور خواہش کا مجموعہ
- خواہشات کی شدت اورکمزوری
- انسانی زندگی میں خواہشات کا مثبت کردار
- 1۔انسانی زندگی کا سب سے طاقتور محرک
- 2۔خواہشات ترقی کا زینہ
- عمل اور رد عمل کا سلسلہ
- خواہشات کا تخریبی کردار
- خواہشات اور طاغوت
- عقل اور دین
- خواہشات کی تباہ کاریاں
- تباہ کا ری کے مراحل
- خواہشات کی تخریبی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ
- 2۔خواہشات گمراہی کا ذریعہ
- 3۔خواہشات ایک مہلک زہر
- 4۔خواہشات آفت اور بیماری
- 5۔خواہشات آزمائشوں کی بنیاد
- 6۔خواہشات فتنوں کی چر اگاہ
- 7۔خواہشات ایک پستی
- 8۔خو اہشات موجب ہلا کت
- 9۔خو اہشات انسان کی دشمن
- 10۔عقل کی بربادی
- خو ا ہشات کی تباہ کاری کا دو سرا مر حلہ
- خواہشات کا قیدی
- خواہشات کی قیدقرآن و حدیث کی روشنی میں
- انسان اور خواہشات کی غلامی
- اللہ نے بھی اسے نظر انداز کردیا
- خواہشات کی تباہیاں قرآن مجید کی روشنی میں
- 1۔زمین کی جانب رغبت
- 2۔آیات خدا سے محرومی
- 3۔شیطان کا تسلط
- 4۔ضلا لت و گمراہی
- 5۔لالچ
- خواہشات کا علاج
- ہوس کی تخریبی طاقت
- خواہشات کی پیروی پر روک اور انکی آزادی کے درمیان
- خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لئے ''عقل ''کا کردار
- عقل اور دین
- امام مو سیٰ کا ظم
- عقل کے تین مراحل
- 1۔معر فت اور حجت آوری
- 2۔اطاعت خدا
- 3۔خواہشات کے مقابلہ کے لئے صبروتحمل(خواہشات کا دفاع)
- عقل اور خواہشات کی کشمکش اور انسان کی آخری منزل کی نشاندہی
- ضعف عقل اورقوت ہوس
- عقل کے لشکر
- لشکر عقل سے متعلق روایات
- پہلی روایت
- دوسری روایت
- روایت کی مختصر وضاحت
- عقل کامل کے فوائداور اثرات
- 1۔حق کے اوپر استقامت
- 2۔دنیا سے دشمنی رکھناکامل عقل کا ثمر ہے
- 3۔خواہشات پر مکمل تسلط
- 4۔حسن عمل اورسلامتی کردار
- عصمتیں
- عصمتوں کے بارے میں مزید گفتگو
- دوسری آیۂ کریمہ
- عصمتوں کی قسمیں
- خوف الٰہی
- خوف ایک پناہ گاہ
- چند واقعات
- حیاء
- ﷲ تعالیٰ سے حیائ
- بارگاہ خدا میں قلت حیا کی شکایت
- دوسری فصل
- 1۔اسکے امور کو درہم برہم کردوںگا
- ٹھوس شخصیت
- عماربن یاسر
- کھوکھلااوربے ہنگم انسان(شخصیت )
- ہوس کے عذاب
- دنیا اپنے خواہشمند کے لئے ایک وبال جان
- خواہشات کی پیروی کے بعد انسان کی دوسری مصیبت
- دنیا انسان کا ایک سایہ
- روایات کی روشنی میں عذاب دنیا کے چند نمونے
- آخرت میں انسان کی سرگردانی وپریشا ں حالی
- 2۔اسکی دنیا کو اسکے لئے مزین کردوںگا
- دنیا کا ظاہر اور باطن
- دنیا اورآخرت کا تقابلی جائزہ
- کلا م امیر المومنین میں دنیاکا تذکرہ
- آپ کے ایک خطبہ کا ایک حصہ
- ب۔دنیا کاظاہری رخ(روپ)
- دنیاوی زندگی کے ظاہر اور باطن کا موازنہ
- دنیا کے بارے میں نگاہوں کے مختلف زاوئے
- طرز نگاہ کا صحیح طریقہ کار
- نفس کے اوپر طرز نگاہ کے اثرات اورنقوش
- محبت یا زہددنیا
- حب دنیا
- حب دنیا ہر برائی کا سر چشمہ
- حب دنیا کا نتیجہ کفر ؟
- حب دنیا کے نفسیا تی اور عملی آثار
- 1۔طولانی آرزو
- 2۔دنیا پر اعتماد اور اطمینان
- 3۔دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا
- آخرت کی نعمتوں کے لئے دنیا ہی میں عجلت پسندی
- زود گذر
- روایات کا تجزیہ
- با طن بیں نگاہ
- زہد
- زاہد ،صابر اور راغب۔
- زہد،تمام نیکیوں کا سرچشمہ
- زہد کے آثار
- 1۔آرزووں میں کمی
- 2۔دنیاوی تاثرات سے نجات اورآزادی
- 3۔دنیاپرعدم اعتماد
- دنیا ایک پل
- اسباب ونتائج کا رابطہ
- زہد وبصیرت
- زہدو بصیرت کا رابطہ
- مذموم دنیا اور ممدوح دنیا
- دنیا سے بچائو
- ب :ممدوح دنیا
- 1۔دنیا آخرت تک پہو نچانے والی
- 2۔دنیا مومن کی سواری
- ج۔اسکے دل کو اسکا دلدادہ بنا دونگاجرم اور سزا کے درمیان تبادلہ
- دنیاداری کے دورخ یہ بھی!
- دل کے اوپر خدائی راستوں کی بندش کے بعض نمونے
- 1۔غبار اور زنگ
- 2۔الٹ،پلٹ
- 3۔زنگ یامُہر
- 4۔مہُر
- 5۔قفل
- 6۔غلاف
- 7۔پردہ
- 8۔سختی
- 9۔قساوت
- دنیا قید خانہ کیسے بنتی ہے ؟
- اہل دنیا
- دنیا کابہروپ
- تیسری فصل
- جو شخص خداوند عالم کی مرضی کو
- اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دیتا ہے
- مرضی خدا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا
- افکار کی تبدیلی میں اسلامی اصطلاحات کا کردار
- فقرواستغنا اور اقدار کے اسلامی اصول
- دور جاہلیت کا نظام قدروقیمت
- قدروقیمت کا اسلامی نظام
- اسلامی روایات میں استغنا کا مفہوم
- اقدار کے نظام میں انقلاب
- نفس کی بے نیازی
- بے نیازی(استغنا)کے ذرائع
- 1۔یقین
- 2۔تقویٰ
- 3۔شعور
- حیات انسانی میں بے نیازی کے آثار
- 2۔ضمنت السمٰوات
- توفیق
- عالم غیب اور عالم شہود(ظاہر)کے درمیان رابطہ
- حرکت تاریخ کے سلسلہ میں غیبی عامل کا کردار
- پہلا مرحلہ
- دوسرا مرحلہ
- تیسرا مرحلہ
- غیبی عامل،مادی عوامل کا منکر نہیں
- تقویٰ اور رزق کا تعلق
- تقویٰ کی بنا پر نجات پانے والے تین لوگوں کا واقعہ
- 3۔کففت علیہ ضیعتہ
- ہدایت کے معنی
- ﷲ بندہ کو بربادی اورضائع ہونے سے کیسے بچاتا ہے ؟
- بصیرت اور عمل
- بصیرت اور عمل کا رابطہ
- 1۔ عمل صالح کا سرچشمہ بصیرت
- 2۔بصیرت کی بنیاد عمل صالح
- دوسرا رخ
- بے عملی سے خاتمۂ بصیرت
- فقدان بصیرت برے اعمال کا سبب
- خلاصۂ کلام






