درس عقائد
 0%
0%
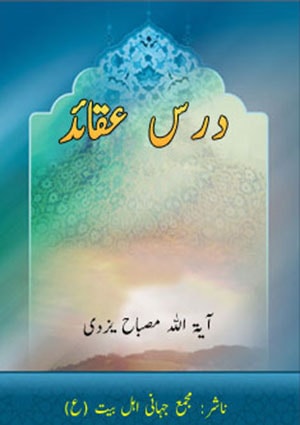 مؤلف: آیت اللہ مصباح یزدی مدظلہ العالی
مؤلف: آیت اللہ مصباح یزدی مدظلہ العالی
زمرہ جات: متفرق کتب
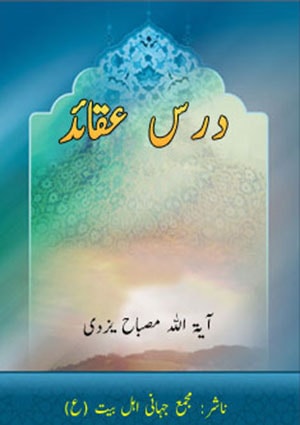
مؤلف: آیت اللہ مصباح یزدی مدظلہ العالی
زمرہ جات:
ڈاؤنلوڈ: 5103
تبصرے:
- حرف اول
- پیش لفظ
- مقدمہ مولف
- پہلا درس
- دین کیا ہے؟
- ١۔دین کا مفہوم
- ٢۔اصول دین اور فروع دین
- ٣۔جہاں بینی(تصور خلقت) اور آئیڈیالوجی ۔
- ٤۔الٰہی و مادی جہان بینی۔
- ٥۔آسمانی ادیان اور ان کے اصول۔
- ١۔ خدائے یکتا پر اعتقاد ۔
- نتیجہ
- سوالات
- دوسرا درس
- دین میں تحقیق
- تحقیق کے عوامل
- دین میں تحقیق۔
- ایک شبہ کا حل۔
- سوالات
- تیسرا درس
- انسان بن کے جینے کی شرط
- مقدمہ
- انسان کمال طلب ہے۔
- انسان کا کمال، عقل کی پیروی میں ہے۔
- عقل کے احکام عملی کو مبانی نظری کی ضرورت ہے
- نتیجہ۔
- سوالات
- چوتھا درس
- جہان بینی کے بنیادی مسائل کا راہ حل
- مقدمہ
- شناخت کی قسمیں ۔
- معرفت کی قسمیں
- تنقید۔
- نتیجہ
- سوالات
- پانچواں درس
- خدا کی معرفت
- مقدمہ
- حضوری اور حصولی معرفت۔
- فطری شناخت۔
- نتیجہ
- سوالات
- چھٹا درس
- خدا شناسی کا آسان راستہ
- خدا شناسی کے راستے
- آسان راستہ کی خصوصیات۔
- آشنا نشانیاں ۔
- سوالات
- ساتواں درس
- واجب الوجود کا اثبات
- مقدمہ
- متن برہان۔
- واجب الوجود ہو۔
- امکان اور وجوب۔
- علت اور معلول۔
- علتوں کے تسلسل کا محال ہونا۔
- تقریر برہان۔
- سوالات
- آٹھواں درس
- خدا کی صفات
- مقدمہ
- خدا کا ازلی و ابدی ہونا۔
- صفات سلبیہ۔
- موجودات کو وجود بخشنے والی علت۔
- وجود بخشنے والی علت کی خصوصیات۔
- سوالات
- نواں درس
- صفات ذاتیہ
- مقدمہ
- صفات ذاتیہ اور فعلیہ۔
- صفات ذاتیہ کا اثبات۔
- حیات۔
- علم۔
- قدرت۔
- سوالات
- دسواں درس
- صفات فعلیہ
- مقدمہ
- خالقیت۔
- ربوبیت۔
- الوہیت۔
- سوالات
- گیارہواں درس
- بقیہ صفات فعلیہ
- مقدمہ
- ارادہ۔
- حکمت۔
- نتیجہ
- کلام الٰہی۔
- صدق۔
- سوالات
- بارہواں درس
- انحراف کے اسباب کی تحقیق
- مقدمہ
- انحراف کے اسباب۔
- ١۔روحی اسباب
- ٢۔اجتماعی اسباب۔
- ٣۔ فکری اسباب۔
- انحرافی اسباب کا سد باب۔
- سوالات
- تیرہواں درس
- چند شبہات کا حل
- نا محسوس مو جودپر اعتقاد
- خدا پر ایمان رکھنے کے سلسلہ میں جہل اور خوف کاکردار۔
- کیا قاعدہ علیت ایک قاعدہ کلی ہے۔
- علوم اجتماعی کے نتائج۔
- سوالات
- چودہواں درس
- مادی جہان بینی اور اس پر تنقید
- مادی جہان بینی کے اصول
- پہلی اصل ۔
- دوسری اصل ۔
- تیسری اصل
- چوتھی اصل ۔
- سوالات
- پندرہواں درس
- ماٹریالیسم ڈیالٹیک اور اس پرتنقید
- مکینکی اورڈیالٹیکی ماٹریالیسم
- تنقید۔
- قاعدہ جہش۔
- تنقید۔
- قاعدہ نفی نفی۔
- تنقید۔
- سوالات
- سولہواں درس
- خدا کی لاثانیت
- مقدمہ
- خدا کی لاثانیت پر برہان و دلیل۔
- نتیجہ۔
- سوالات
- سترہواں درس
- توحید کے معانی
- مقدمہ
- ١۔تعدد کی نفی
- ٢۔ ترکیب کی نفی
- ٣۔زائد برذات صفات کی نفی۔
- ٤۔توحید افعالی۔
- ٥۔تاثیر استقلالی۔
- دو مہم نتیجے۔
- شبہ کا جواب۔
- سوالات
- اٹھارہواں درس
- اٹھارہواں درس
- جبرو اختیار
- مقدمہ
- اختیار کی وضاحت۔
- شبہات کے جوابات۔
- سوالات
- انیسواں درس
- دین کیا ہے
- قضاوقدر کا مفہوم
- قضا و قدر علمی و عینی۔
- انسان کے اختیار سے قضا و قدر کا رابطہ۔
- متعدد علتوں کے اثر انداز کی قسمیں۔
- شبہ کا جواب۔
- قضا و قدر پر اعتقاد کے آثار۔
- سوالات
- بیسواں درس
- عدل الٰہی
- مقدمہ
- مفہوم عدل۔
- نتیجہ۔
- دلیل عدل الٰہی ۔
- چند شبہات کا حل۔
- سوالات
- اکیسواں درس
- اکیسواں درس
- مسائل نبوت پر بحث کرنے کے نتائج
- مقدمہ
- اس حصہ کے مبا حث کا ھدف
- علم کلام میں تحقیق کی روش
- سوالات
- بائیسواں درس
- بشر کو وحی اور نبوت کی ضرورت
- بعثت انبیاء (ع) کی ضرورت۔
- بشری علوم کی ناکامی۔
- بعثت انبیاء (ع) کے فوائد۔
- سوالات
- تیئسواں درس
- چند شبہات کا حل۔
- کیوں بہت سے لوگ انبیاء ٪ کی ہدایت سے محروم ہو گئے؟
- کیوں خدا نے انحرافات اور اختلافات کا سد باب نہیں کیا؟
- کیوں انبیاء ا لٰہی صنعتی اور اقتصادی امتیازات سے سرفراز نہ تھے؟
- سوالات
- چوبیسواں درس
- عصمت انبیاء (ع)
- وحی کے محفوظ رہنے کی ضرورت۔
- عصمت کی دوسری قسمیں ۔
- انبیاء (ع) کی عصمت ۔
- سوالات
- پچیسواں درس
- پچیسواں درس
- انبیاء (ع)کے معصوم ہونے کی دلیلیں
- مقدمہ
- عصمت انبیاء (ع)پر عقلی دلائل۔
- عصمت انبیاء (ع) پر نقلی دلائل۔
- عصمت انبیاء (ع) کا راز ۔
- سوالات
- چھبیسواں درس
- چند شبہات کا حل۔
- پہلا شبہ یہ ہے
- اسی شبہ کا جوا ب
- دوسراشبہ یہ ہے
- اس شبہ کا جواب یہ ہے
- تیسرا شبہ یہ ہے
- اس شبہ کا جواب یہ ہے
- چوتھا شبہ یہ ہے
- اس شبہ کا جواب یہ ہے
- پانچواں شبہ یہ ہے
- ان شبہات کا جواب یہ ہے
- چھٹا شبہ یہ ہے
- اس شبہ کا جواب یہ
- ساتواں شبہ یہ ہے
- اس شبہ کا جواب یہ ہے
- آٹھواں شبہ یہ ہے
- ا س شبہ کا جواب یہ ہے
- نواں شبہ یہ ہے
- اس شبہ کا جواب یہ ہے
- دسواں شبہ یہ ہے
- اس شبہ کا جواب یہ ہے
- سوالات
- ستائیسواں درس
- معجزہ
- نبوت کو ثابت کرنے کے را ستے۔
- معجزہ کی تعریف۔
- خارق عادت امور۔
- الٰہی خارق عادت امور۔
- انبیاء (ع) کے معجزات کی خصوصیات۔
- سوالات
- اٹھائیسواں درس
- چند شبہات کا حل۔
- پہلا شبہ یہ ہے
- دوسرا شبہ یہ ہے
- تیسرا شبہ یہ ہے
- مزید وضاحت
- چوتھا شبہ یہ ہے
- نتیجہ
- سوالات
- انتیسواں درس
- انتیسواں درس
- انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات
- انبیاء علیہم السلام کی کثرت۔
- انبیاء علیہم السلام کی تعداد۔
- نبوت اور رسالت۔
- اولوالعزم انبیاء علیہم السلام۔
- چند نکات۔
- سوالات
- تیسواں درس
- انبیاء علیہم السلام اور عوام
- مقدمہ
- انبیاء علیہم السلام کے مقابل میں لوگوں کا کردار۔
- انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کے اسباب۔
- انبیاء علیہم السلام سے ملنے کا طریقہ۔
- الف: تحقیر و استہزاء
- ب:ناروا بہتان
- ج: مجادلہ اور مغالطہ
- انسانی معاشروں کی تدبیر میںبعض سنت الٰہی۔
- سوالات
- اکتیسواں درس
- پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم
- مقدمہ
- پیغمبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم کی رسالت کا اثبات۔
- سوالات
- بتیسواں درس
- اعجاز قرآن
- قرآن کا معجزہ ہونا۔
- اعجاز قرآن کی صورتیں۔
- الف ۔قرآن کی فصاحت و بلاغت۔
- ب۔ قرآ ن لانے والے کا اُمیِّ ہونا۔
- ج۔ اتفاق نظر اور عد م اختلاف۔
- وضاحت
- سوالات
- تیتیسواں درس
- قرآن کا تحریف سے محفوظ رہن
- مقدمہ
- قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا۔
- قرآن سے کسی چیز کا کم نہ ہونا۔
- سوالات
- چونتیسواں درس
- اسلام کا جہانی اور جاودانی ہونا
- مقدمہ
- اسلام کا جہانی ہونا۔
- اسلام کے جہانی ہونے پر قرآنی دلائل۔
- اسلام کا جاودانی ہونا۔
- چند شبہات کا حل۔
- سوالات
- پینتیسواں درس
- خاتمیت
- مقدمہ
- خاتمیت پر قرآنی د لائل۔
- خاتمیت پر روائی دلائل۔
- ختم نبوت کا راز۔
- چند شبہات کے جوابات۔
- سوالات
- چھتیسواں درس
- امامت
- مقدمہ
- مفہوم امامت۔
- سوالات
- سیتیسواں درس
- امام علیہ السلام کی احتیاج
- مقدمہ
- وجودا مام علیہ السلام کی ضرورت۔
- سوالات
- اڑتیسواں درس
- منصب امام
- سوالات
- انتالیسواں درس
- عصمت اور علم امام
- مقدمہ
- عصمت امام ۔
- علم امام۔
- سوالات
- چالیسواں درس
- حضرت مہدی (عج)
- مقدمہ
- جہانی حکومت الٰہی۔
- وعدۂ الٰہی۔
- چند روایتیں۔
- غیبت ِاور اُس کا راز ۔
- سوالات
- اکتا لیسواں درس
- شنا خت عا قبت کی اہمیت
- مقدمہ
- قیا مت پر اعتقا د کی ا ہمیت وضرورت۔
- قیا مت کے مسئلہ پر قر آن کی تا کید۔
- نتیجہ۔
- سوا لا ت
- بیا لیسوا ں درس
- مسئلہ قیامت اور مسئلہ رو ح کا با ہمی رابطہ
- زندہ مو جود ا ت کی وحد ت کا معیا ر۔
- انسان کے وجود میں روح کا مقام(کردار)
- سوا لات
- تینتا لیسواں درس
- روح کا غیر محسوس ہونا (روح کا مجرد ہونا)
- مقدمہ
- روح کے غیر محسوس ہو نے پر عقلی دلائل
- قرآنی دلائل۔
- نتیجہ کلام۔
- سوالات
- چوّالسیوا ں درس
- قیامت کا اثبات
- مقدمہ
- برہان حکمت۔
- حکمت کے خلاف کام ہوتا۔
- برہان عدا لت۔
- سوالات
- پینتالیسواں درس
- قرآن میں قیامت کا تذکرہ
- مقدمہ
- قیامت کا انکار بے دلیل ہے۔
- قیامت کے ما ند دوسرے حو ادث
- ( الف )سبزوں کا اگنا۔
- (ب)اصحا ب کہف کا سو نا۔
- (ج) حیو انا ت کا زندہ ہو نا ۔
- (د)اسی دنیا میں بعض انسانوں کا زندہ ہو نا ۔
- دوسر واقعہ
- سوا لا ت
- چھیا لیسواں درس
- منکرین کے شبہات کے لئے قرآن کا جواب
- ١۔فنا ہونے کے بعد دوبارہ پلٹنے کا شبہ۔
- ٢۔بدن میں دوبارہ حیات پانے کی صلاحیت نہ ہونے کا شبہ۔
- ٣۔ فاعل کی قدرت کے بارے میں شبہ۔
- ٤۔ فا عل کے علم کے با رے میں شبہ۔
- سوالات
- سینتالیسواںدرس
- قیامت کے بارے میں خدا کا وعدہ
- مقدمہ
- خدا کا سچا(حتمی)وعدہ
- عقلی دلا ئل کی طر ف اشا رہ
- سوا لا ت
- اڑ تا لیسواں درس
- عالم آخر ت کی خصو صیا ت (آخرت کی پہنچان)
- مقدمہ
- عقل کی روشنی میں آخرت کی خصو صیا ت۔
- توضیح
- سوالات
- انچاسواں درس
- موت سے قیامت تک
- مقدمہ
- ہر ایک کو موت آنی ہے۔
- روح قبض کرنے والا
- قبض روح آسان ہے یاسخت؟
- مو ت کے وقت ایما ن اور تو بہ کا قبول نہ ہو نا
- دنیا میں واپسی کی آرزو۔
- عالم برزخ۔
- سوالات
- پچاسواں درس
- قرآن مجید میں قیامت کا نقشہ
- مقدمہ
- زمین دریا اور پہاڑوں کی حالت
- آسمانوں اور ستاروں کی کیفیت
- موت کا صور۔
- زندگی اور آغاز قیامت کا صور۔
- الٰہی حکومت کا ظہور اور سببی ونسبی رشتوں کا خاتمہ۔
- خدائی عدالت کامقدمہ(محاکمہ)
- ابدی ٹھکا نے کی طرف روانگی
- جنت۔
- جہنم
- سو الات
- اِکیاو نو اں درس
- دنیا کا آخر ت سے مقابلہ
- مقد مہ
- دنیا کا فا نی ہو نا اور آخر ت کا ابدی ہو نا ( ہمیشہ با قی رہنا )
- آخرت میں نعمت اور عذا ب کے ما بین جد ائی
- آخرت کا اصل ہو نا ۔
- دنیا وی زندگی کو انتخا ب کر نے کا نتیجہ ۔
- وضا حت ۔
- سو الا ت
- با ونواںدرس
- دنیا آخر ت کی کھیتی ہے
- مقدمہ
- دنیا آخر ت کی کھیتی ہے
- دنیا کی نعمتیں آخرت کی سعادت (خوشبختی) کا سبب نہیں
- دنیا کی نعمتیں آخرت کی شقاوت ( بد بختی) کاسبب بھی نہیں ہو سکتیں
- نتیجہ کلا م
- سوا لا ت
- تر پنو اں در س
- دنیا و آخرت کے در میان را بطہ کی قسم
- مقدمہ
- را بطہ حقیقی ہے یا قرار دادی (فر ضی)
- قر آنی دلیلیں
- سوا لا ت
- چوّ نواں درس
- ابدی خو شبختی یا بد بختی میں ایمان کا دخل
- مقدمہ
- ایمان اور کفر کی حقیقت
- ایمان اور کفر کی حد(نصاب)
- ابدی خوشبختی یا بد بختی میں ایمان اور کفر کا دخل
- قر آنی دلیلیں
- سو الا ت
- پچپنواں در س
- ایمان اور عمل کا آپس میں رابطہ
- مقدمہ
- ایمان کا عمل سے رابطہ
- عمل کا ایمان سے رابطہ
- نتیجہ
- سو الا ت
- چھپنو ا ں در س
- مقدمہ
- مقدمہ
- انسان کا حقیقی کمال
- عقلی بیان
- خواہش(محرک)اور نیت کا کردار
- سوالات
- ستاو نواں درس
- حبط و تکفیر
- مقدمہ
- ایمان اور کفر کا رابطہ۔
- نیک وبد اعمال کا رابطہ
- سوالات
- اٹھاونواں درس
- مومنین کے امتیازات
- مقدمہ
- ثوا ب میں اضا فہ
- گناہان صغیرہ کی بخشش
- دوسروں کے اعمال سے استفادہ
- سوالات
- انسٹھو اں درس
- شفا عت
- مقدمہ
- شفا عت کا مفہو م
- شفا عت کے اصو ل
- سو الا ت
- سا ٹھو اں درس
- چند شبھات کا حل
- شبہ (١)
- جو اب
- شبہ (٢)
- جو اب
- شبہ(٣)
- جو اب
- شبہ (٤)
- جو اب
- شبہ(٥)
- جوا ب
- شبہ(٦)
- جو اب
- شبہ(٧)
- جو اب
- سو الا ت






