کامیابی کے اسرار ج 1 جلد ۱
 0%
0%
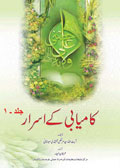 مؤلف: آیت اللہ سید مرتضی مجتہدی سیستانی
مؤلف: آیت اللہ سید مرتضی مجتہدی سیستانی
: عرفان حیدر
ناشر: الماس پرنٹرز قم ایران
زمرہ جات: متفرق کتب
صفحے: 259
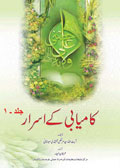
مؤلف: آیت اللہ سید مرتضی مجتہدی سیستانی
: عرفان حیدر
ناشر: الماس پرنٹرز قم ایران
زمرہ جات:
مشاہدے: 163290
ڈاؤنلوڈ: 5516
تبصرے:
- انتساب
- مقدمہ مترجم
- پیش گفتار
- فکر کی اہمیت
- فکر کی پرواز
- فکر کی اہمیت کے کچھ راز
- گناہ کے بارے میں فکر کرنے کا اثر
- تفکر ایمان و یقین میں اضافہ کا باعث ہے
- تفکر بصیرت اور دور اندیشی کا وسیلہ
- روزۂ فکر
- صحیح و سالم فکر کے طریقے
- 1۔ دقت اور سوچ سے فکر کو سالم کر نا
- 2 ۔ پر خوری سے پر ہیز کرنا
- 3 ۔ فکری اشتباہات میں مبتلا افراد سے پر ہیز کرنا
- نتیجۂ بحث
- مشورہ کرنے کی ضرورت
- مشورہ ترقی و پیشرفت کااہم ذریعہ
- کس کے ساتھ مشورہ کریں ؟
- مشورہ کے بعد اس پر عمل کریں
- مشورہ نہ کرنے کا انجام
- نتیجۂ بحث
- بہتر ین ہدف کا انتخاب کریں
- ہدف کے نتیجہ پر توجہ کریں
- انسان کی تخلیق کا کیا ہدف ہے؟
- مقصد وہدف تک پہنچنے کے ذرا ئع
- 1 ۔ اپنے ہدف کے حصول کی امید
- ایک نکتہ کا تذکر
- 2 ۔ ہدف کے حصو ل میں طلب و جستجو کا کردا ر
- 3 ۔ بزرگ ہستیوں کی خدمت میں رہنا
- 4 ۔ عالی اہداف تک پہنچنے کے لئے نفس کی مخالفت
- 5 ۔ عظیم اہداف تک پہنچنے کے لئے اہل بیت سے توسل
- نتیجۂ بحث
- ارادہ کی اہمیت
- ارادہ سے پہلے اخلاص
- اپنے ارادہ کو صحیح سمت دیں
- بلند حوصلہ رکھیں
- اپنے ارادہ پر عمل کریں
- قوت ارادہ کے ذریعہ اپنی طبیعت پر غالب آنا
- ملّا صالح مازندرانی، ایک پختہ ارادہ کے مالک شخص
- اپنے ارادہ اور نیت کو تقویت دینا
- ارادہ کو تقویت دینے کے طریقے
- 1 ۔ ذوق و شوق آ پ کے ارادہ کو تقویت دیتا ہے
- 2 ۔ امید و آرزو سے ہمت میں اضافہ ہو تا ہے
- 3 ۔ خدا سے پختہ ارادہ و بلند ہمت کی دعا کریں :
- نتیجہ ٔبحث
- نظم وضبط کی اہمیت
- نظم و ضبط آشفتگی کو ختم کر تا ہے
- نو جوانوں کی صحیح نظم و ضبط میں مدد کریں
- نظم و ضبط
- وقت سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ
- مرحوم شیخ انصاری کا منظم پروگرام
- نتیجۂ بحث
- وقت سے استفادہ کرنا
- علامہ مجلسی کا وقت سے استفادہ کر نا
- وقت ضائع نہ کریں
- بیکاری کا نتیجہ
- وقت تلف کرنا یا تدریجی خود کشی
- اپنے ماضی سے عبرت حاصل کریں
- دوسروں کے ماضی سے سبق سیکھیں
- اپنا وقت دوسروں کے شخصی اہداف کے لئے ضائع نہ کریں
- فرصت سے استفادہ کریں
- آخری سانس تک زندگی سے استفادہ کریں
- نتیجہ ٔ بحث
- صالحین سے ہمنشینی کی اہمیت کا راز
- جن افراد کی صحبت روح کی تقویت کا باعث ہے
- 1 ۔ علماء ربانی کی صحبت
- 2 ۔ صالحین کی صحبت
- اپنے ہمنشینوں کو پہچانیں
- جن افراد کی صحبت ترقی کی راہ میں رکاوٹ
- 1 ۔ چھوٹی سوچ کے مالک افراد کی صحبت
- 2 ۔ گمراہوں کی صحبت
- 3 ۔ خواہش پرستوں کی صحبت
- ۴ ۔ شکّی لوگوں کی صحبت
- نتیجۂ بحث
- روحانی تکامل کے لئے تجربہ کی ضرورت
- تجربہ اور سر پرستی وحکومت
- علمی و صنعتی مسائل میں تجربہ
- تجربہ عقل کی افزائش کا باعث
- تجربہ ، فریب سے نجات کا ذریعہ
- مشکلات میں دوستوں کو پہچاننا
- تجربہ سے سبق سیکھیں
- دوسروں کے تجربات سے استفادہ کریں
- دوسروں کے تجربہ سے استفادہ کرنے کا طریقہ
- تجربات فراموش نہ کریں
- نتیجہ ٔ بحث
- مخالفت نفس یا نفس پر حکومت
- عقل پر نفس کا غلبہ
- نفس کا معالجہ
- اصلاح نفس کے لئے دعا
- مخالفت نفس کی عادت
- اصلاح نفس کے ذریعہ روحانی قوت سے استفادہ کرنا
- قدرت نفس
- نتیجۂ بحث
- صبر اسرار کے خزانوں کی کنجی
- صبر واستقامت ارادہ کی تقویت کا باعث
- صبر حضرت ایوب (ع)
- اپنے نفس کو صبر واستقامت کے لئے آمادہ کرنا
- مرحوم علی کَنی اور ان کے صبر کا نتیجہ
- صبر قوت وقدرت کا باعث
- نتیجۂ بحث
- اہمیت اخلاص
- اخلاص کا نتیجہ
- صاحب جواہر الکلام کا اخلاص
- ہم کیا صاحب اخلاص بن سکتے ہیں ؟
- زحمت اخلاص
- نتیجۂ بحث
- علم ارتقاء کا ذریعہ
- تحصیل علم میں ارادہ کی اہمیت
- حصول علم کے لئے گناہوں کو ترک کرنا
- کون سا علم روحانی تکامل کا باعث ہے؟
- علم کی ترویج معنوی کمالات کا ذریعہ
- نتیجۂ بحث
- انسان کی ترقی میں توفیق کا کردار
- سعادت کے چار بنیادی ارکان
- نیت ، قدرت، توفیق، منزل تک پہنچنا۔
- توفیق نیکیوں کی طرف ہدایت کا ذریعہ
- کامیاب اشخاص
- توفیق حاصل کرنے کے ذرائع
- 1۔ کسب توفیق کے لئے دعا کرنا
- ایک اہم نکتہ
- 2۔ ماں باپ کی دعا توفیق کا سبب
- 3۔ توفیق کے حصول کے لئے جستجو اور کوشش کرنا
- 4۔ خدا کی نعمتوں میں تفکر، توفیق الٰہی کا سبب
- نتیجۂ بحث
- یقین کی اہمیت
- یقین کے آثار
- 1۔ یقین دل کو محکم کرتا ہے
- مجلس مباہلہ میں حاضری
- ۲۔ یقین اعمال کی اہمیت میں اضافہ کا ذریعہ
- 3۔ یقین آپ کے باطن کی اصلاح کرتا ہے
- یقین کو متزلزل کرنے والے امور
- 1۔ شک و شبہ
- 1۔ شک و شبہ
- 2۔ گناہ
- یقین کھودینا
- تحصیل یقین کے ذرائع
- 1۔ کسب معارف
- 1 ۔ کسب معارف
- 2۔ دعا اور خدا سے راز و نیاز
- 3- تہذیب و اصلاح نفس
- نتیجۂ بحث






