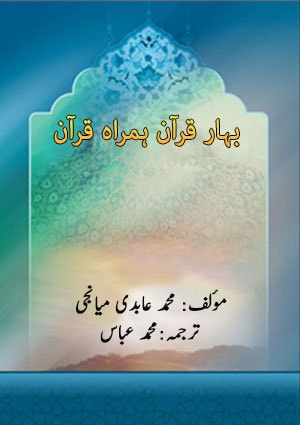بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
پہلا جزء :تقوا
(الم ذَالِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمِا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَ بِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُوْلَئكَ عَلىَ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
)۔
الف لام میم۔ یہ کتاب ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لیے۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیاگیا ہے، ان پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔
۱۔ تقوا کیا ہے ؟
اس کے بارے میں خدا وند متعال ان آیات میں فرماتا ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور اہل تقوا کی ہدایت کا سبب ہے پھر لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کرتا ہے ۔ ۱۔ اہل تقوا ۲۔ کافر ۳ ۔ منافق اور اس کے بعد ۔۔متقین کے پانچ صفات بیان کرتا ہے ۔
۱ ۔ غیب پر ایمان رکھنا ۔۲۔ خدا کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا ۔۳۔ لوگوں کے ساتھ رابطہ یعنی انفاق کرنا ۔
۴۔ تمام پیغمبروں پر ایمان کے ساتھ الہی برناموں پر ایمان رکھنا ۔۵ ۔ قیامت پر ایمان رکھنا ۔ اور آخر میں فرماتا ہے کہ یہ سب خدا کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں اب دیکھیں تقوا کیا ہے ؟
امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقوا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا :
فَقَالَ لَا يفْقِدُكَ اللَّهُ حَيْثُ أَمَرَكَ وَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ
خدا وند عالم جب کسی چیزکا حکم دے تو اس وقت غایب نہیں ہونا چاہیے یعنی اس حکم کو بجا لانا چاہیے اور جب خداوند عالم کسی چیز سے منع کرے تو حاضرنہیں ہونا چاہیے یعنی حرام چیز سے پرہیز کرنا چاہیے ۔
تقوا ملاحظہ خدا ہے : یعنی انسان ہر کام میں خداوند متعال کو مد نظر رکھے جس چیزمیں خدا کی ناراضگی ہو اس کو انجام نہ دے اور جس چیز میں خدا کی خوشنودی ہو اس کو بجا لائے ۔
تقوا یعنی جو چیز بھی خدا کو نا پسند ہے اس سے دودری اختیار کرنا اور ہر وہ چیز جس میں خدا کی ناراضگی ہو اس سے دوری کرنے کا نام تقوا ہے ۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا :
التقوی اجتناب
یعنی تقوا پرہیزگاری کا نام ہے ۔
ألتّقوى أن يتّقى المرء كلّما يؤثمه
یعنی تقوا انسان کا اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے ۔ تقوا کے معنی گناہ اور خطرہ سے اپنی حفاظت کرنا ۔ انسان اپنے اندرونی شہوات پر کنٹرول کرتے ہوئے خدا وند عالم کے حکم پر عمل پیرا ہو اور شہوات اور غصہ پر کنٹرول کرے ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے اندرونی شہوات اور غصہ پر کنٹرول نہ کرسکے اور اپنے نفس پر قابو نہ پاکرمَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ
کا مصداق بن جائے ۔
اسی وجہ سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا :
مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ كَانَ تَقِيّاً
.
جو انسان اپنی شہوت پر غلبہ پائے وہ متقی ہے ۔ یعنی انسان اپنے شہوات نفسانی پر کنٹرول کر سکے تو یہی تقوا ہے ۔
اسی طرح انسان کا نفس ہر غیر خدا سے آزاد ہو جائے گا لیکن بے تقوا انسان خدا وند عالم سے آزاد ہو گا اور اپنے نفس یا دوسروں کا اسیر بن جائے گا ۔ یہی وجہ ہے کا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی گنا ہ کرتا ہے وہ آزاد ہے یعنی اگروہ بندہ خدا ہوتا تو گناہ نہیں کرتا ۔
امیر المؤمنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ ۔۱۷۳ ۔۸۳ ۔۱۱۴ ۔۱۸۲ ۔۱۹۴ ۔۱۹۵ ۔۱۹۶ ۔ میں فرماتے ہیں ۔
تقوا ایک قلعہ ہے جسے کوئی بھی شکت نہیں دے سکتا ہے اور فیجور قلعہء شکست پزیر ہے جو ا اپنے اہل کی حفاظت نہیں کرتا ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس قلعہ فیجور میں امن حاصل کرے تو وہ امنیت حاصل نہیں کرسکتا ہے ۔
۲۔ سر چشمہ تقوا :
الف ۔ دین
دین اسلام تقوا ایجاد کرنے کا بہت بڑا سبب ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں ایمان کے عنوان سے آیات میں بھی اسی سرچشمہ اور سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ۔
امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا
:التَّقْوَى ثَمَرَةُ الدِّين
یعنی تقوا دین کا پھل ہے ۔
ب ۔ محاسبہ نفس :
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم نے ابو ذر کو وصیت کی ! اے ابوذر لوگ اہل تقوا نہیں بن سکیں گے سوای اس کے کہ سخت ترین محاسبہ کریں کہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لائے ہیں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے
پ ۔ قلب عارف :
دل ! پیغمبر کی نگاہ میں اگر شناخت خدا اور عظمت و صفات خدا ! انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہ دل خدا محوری اور تقوا کے لئے ایک عظیم معدن ہوگا
۔لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَ مَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِين
یعنی ہر چیز کے لئے کوئی معدن ہوتا ہے اور تقوا کا معدن عارفوں کے دل ہیں ۔
ت ۔شبہہ سے پرہیز :
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم نے فرمایا :متقین وہ ہیں جو تقوا الہی اختیار کریں اس چیز میں جس میں تقوا لازم نہیں ہے کیونکہ اس سے ڈر ہے کہ وہ شبہہ وغیرہ میں مبتلا ہو جائے ۔
ج ۔ عبادت :
عبادت میں اہم ترین چیز انسان کو اپنی روح کو تقویت دینا اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا ہے جیسے مال کا خرچ کرنا
روزہ رکھنا نماز پڑھنا وغیرہ ان میں سے ہر چیز تقوا الہی کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔
ح ۔ قیامت پر اعتقاد رکھنا :
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں قیامت پر ایمان اور متقین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں
۔ (و با الآخرة هم یوقنون
) ۔اس اعقاد سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے
۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا
:من اکثر من ذکر الآخرة قلت معصیته
اگر انسان آخرت کوزیادہ یاد کرے تو گناہ میں کمی آجاتی ہے یعنی موت کو زیادہ یاد رکھنے سے انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں ۔
خ ۔ خدا کی یاد :
اگر لوگ عظمت خدا او رنعمت خدا کو یاد کرتے تو سیدھے راستے کی طرف پلٹ جاتے اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے لیکن ان کے دل بیمار اور انکی آنکھیں مریض ہیں
سورہ بقرہ میں خدا کی یاد کو عملی طور پر اہل تقوا کی خصوصیات کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے یعنی قیامت پر ایمان رکھنا اہل تقوا کی نشانی ہے اس میں سے نماز ایک مصداق ہے انسان اس نماز کو ہمیشہ ادا کرے تو احساس کرتا ہے کہ تمام مخلوقات سے آگے بڑھ گیا ہے اور خدا کے ساتھ باتیں کرنے کی صلاحیت پیدا کرلی ہے اور یہ احساس خد ا محوری میں بہت بڑا کردار رکھتا ہے ۔
۳۔ آثار تقوا :
الف ۔ خیر دنیا و آخرت :
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم نے فرمایا:من رزق التقی رزق خیر الدنیا والآخرة
جسے بھی رزق تقوا ملے گا اسے خیر دنیا و آخرت نصیب ہو گیا ۔
ب۔ گروہ خدا میں شامل ہونا :
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا :أيسرّك أن تكون من حزب اللّه الغالبين إتّق اللّه سبحانه فى كلّ أمرك
کیا الل تعالی کے گروہ میں شریک ہو جاؤ تو خوش نہیں ہو ں گے پس تقوا اختیار کرو ۔
پ ۔ گناہوں کی مغفرت :
(وَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَِّاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
)
اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا ۔
ت ۔ عزت :
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ و السلم نے فرمایا :مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ
.
اگر کوئی لوگوں میں عزیز ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوا الہی اختیار کریں ۔
ث ۔ امور میں سہولت و آسانی :
اگر کوئی تقوا الہی کو اپنا شیوہ بنائے تو خدا وند عالم اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے
(مشکلات سے) نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو
دوسرا جزء: روزہ داری :
(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون
)۔
اے ایمان والو! تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو ۔
۱۔ روزہ مؤمنین کے لئے :
روزہ اہم ترین عبادات میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں روزہ کے واجب ہونے پر تاکید ہو ئی ہے اور اس روزہ کا فلسفہ بھی تقوا الہی بیان ہوئی ہے ۔ روزہ روح انسان کی تقویت اور پرہیز گاری کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزہ میں تمام مشکلات کے ساتھ اس گرمی کو برداشت کرنا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روزہ کے دریعے سے انسان کی روح کو آمادہ کیا جاتا ہے ۔ اس آیت میں چند نکتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے ۔
۱۔ مؤمنین کو مخاطب قرار دے کر یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اس روزہ داری کا لاذمہ ایمان ہے ۔
۲۔ آپ سے پہلے والی امت بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ ان کے اصل ہونے پر تاکید ہو جائے ۔
۳۔ اور اس عمل کے لئے انسان کو تقوا کی وصیت کی گئی ہے ۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :لذة ما في النداء أزالت تعب العبادة و العناء
.
لذت خطاب
(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ
)فرماکر سختی اور ر نج کو انسان سے دور کیا گیا ہے ۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : رمضان کے روزے صرف پہلے والے انبیاء پر ہی واجب تھے اور ان کی امت پر واجب نہیں تھے
امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا : خدا وند عالم نے ہمیں روزہ ماہ رمضان کے ساتھ تمام امتوں سے چن لیا ہے
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا :قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ غَيْرَ الصِّيَامِ هُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ
خدا وند عالم کا فرمان ہے کہ فرزند آدم جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے یعنی وہ عمل اسی کے لئے ہی ہے لیکن روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں ۔
۲۔ روزہ کیوں واجب ہے ؟
روزہ واجب ہونے کی اہم ترین دلیل یہی آیت ہے جو کہ بیان ہوئی ہے روزہ اس لئے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیز گار بن جاؤ اگر کوئی روزہ رکھتاہے اور حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے جو اس کے نفس کے لئے اہم ترین چیز کھانا پینا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہی اس کے لئے تقوا ہے جسے خدا وند عالم چاہتا ہے ۔
اسی وجہ سے امیر المؤمنین فرماتے ہیں ۔راس التقوا ترک الشهادة
۔
یعنی اصل تقوا شہوت کو ترک کرنا ہے یعنی جو بھی انسان کا دل چاہتا ہے اس کے خلاف عمل کرنا ۔
رسول خدا نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے فرمایا :اے جابر ! یہ رمضان کا مہینہ ہے جو بھی دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے اور اپنے پیٹ اور شرم گاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح سے خارج نکل جائے گا جس طرح وہ خود اس مہینے سے گزرتا ہے ۔جابر نے عر ض کیا یا رسول اللہ یہ کلام تو بہت ہی خوبصورت ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ شرائط بہت سخت ہے
ایک اور روایت میں آیا ہے کہصيام القلب عن الفكر فى الآثام أفضل من صيام البطن عن الطّعام
روزہ دار اپنی فکر اور دل کو گناہوں سے پاک رکھنا بہتر ہے بھوک میں رہنے سے حقیقت میں گناہوں سے بچنا اصل ہے اور کھانے پینے سے پرہیز کرنا فرع ہے یہی تقوا کا اصلی ہدف اور مقصد ہے ۔
اسی وجہ سے اگر اصل اور فر ع کی جگہ تبدیل ہو جائے تو اصلی مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر روزہ دار اپنے ہدف اور مقصد کو کھو دے تو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ۔
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے :
چہ بسیار روزہ داری کہ بہرہ اش از روزہ گرسنگی و تشنگی است
و چہ بسیار شب بیداری کہ بہرہ اش از قیام بیداری است
یعنی بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں اور بہت سارے شب بیداری کرنے والے ایمان اور تقوا نہ ہونے کی وجہ سے صرف انکے جاگے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ۔
پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان تقوا و پرہیز گاری کے ساتھ روزہ رکھے تو اس سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کے سانس بھی تسبیح و عبادت شمار ہوتی ہے ۔
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم کا فرمان ہے
:الصَّائِمُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ نَائِماً عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً
روزہ دار اگر بستر پر سو بھی جائے عبادت شمار ہوتا ہے یہ اسوقت تک عبادت شمار ہوتا ہے جب تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے ۔
تقوا اور پرہیز گاری اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی شرائط جتنی سخت ہوں اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ثواب ملے گا جیسا کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت سخت ہے لیکن اس میں زیادہ ثواب ملے گا اور انسان کے خلوص میں اضافہ ہوگا ۔
اسی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہےفَرَضَ اللَّهُ الصِّيَامَ تَثْبِيتاً لِلْإِخْلَاصِ
.
خداوند عالم نے روزے کو فرض کیا ہے تاکہ اخلاص ثابت رہے یعنی تاکہ اخلاص قائم رہے ۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :أَفْضَلُ الْجِهَادِ الصَّوْمُ فِي الْحَرِّ
.
بہترین جہاد گرمیوں میں روزہ رکھنا ہے ۔اسی طرح کے روزے گناہوں کو ہم سے دور کرسکتے ہیں اورجہنم کی آگ ہمارے درمیان پردہ ہوگا ۔
کسی اور جگہ پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّار
.
روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے ۔
روزہ کے ذریعے سے ہم شیطان کو ناکام بناتے ہیں اور اس کے چہرے کو کالا کرسکتے ہیں ۔
امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی ہماری جانیں آپ پر فدا ہو جائیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے شیطان ہم سے دور ہو جائے ؟ تو امام علی نے فرمایا روزہ رکھنے سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور صدقہ دینے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور خدا کی راہ میں دوستی اور نیک کام انجام دینے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور استغفار کرنے سے شیطان کے دل کی رگیں کٹ جاتی ہیں۔
۳۔ روزہ کے آثار :
روزہ کے واجب ہونے کی دلیل کے علاوہ اس کے بہت سارے آثار بھی ہیں ان میں سے بعض درجہ ذیل ہیں ۔
الف ۔ یقین پیدا ہونا :
حدیث معراج میں ہم پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم خدا وند متعال سے سؤال کرتے ہیں روزے کی جائیداد کیاہے ؟
روزہ کی حکمت کو ارث کے طور پر لیتے ہیں اور حکمت معرفت کو ارث کے طور پر لیتی ہے اور معرفت یقین کو ارث کے طور پر لیتی ہے اور جب بندہ یقین تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ دن کو وہ سختی سے گزارے یا آرام سے گزارے ۔
ب ۔ آرامش قلب :
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں : َالصِّيَامُ وَ الْحَجُّ تَسْكِينُ الْقُلُوب
۔
روزہ اور حج دلوں کو آرام پہنچاتے ہیں ۔
پ ۔ اجتماعی آثار :
ایک دن ہشام بن حکم نے امام صادق علیہ السلام سےشریعت میں روزے کے واجب ہونے کی علت کی پوچھا تو امام نے فرمایا: خدا وند متعال نے روزہ کو واجب قرار دیا ہے تاکہ فقیر اور امیر کے درمیان مساوات قائم ہو جائے یہ اس وجہ سے ہیں کہ ثروتمند بھوک کو احساس کرسکیں اور فقیر پر رحم کریں امیر حضرات جب بھی کوئی چیز چاہتے ہیں تو وہ مل جاتی ہیں لذا خداوند متعال یہی چاہتا ہے کہ وہ بندوں کے درمیان مساوات برقرار رہے اور بھوک اور درد کا مزہ کو چکھائے تاکہ امیروں کے دل غریبوں کے لئے دکھ جائے اور ان پر رحم کریں
ت ۔ سلامتی کے آثار :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے :وَ قَالَ النَّبِيُّ صُومُوا تَصِحُّوا
.
روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو جاؤ ۔
ث ۔ دعا کا قبول ہونا :
امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا :دَعْوَةُ الصَّائِمِ تُسْتَجَابُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ
.
۔روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے ۔
ج ۔ مغفرت :
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم نے فرمایا :مَنْ صَامَ يَوْماً تَطَوُّعاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَة
..
جو بھی اپنی اختیار سے خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک دن روزہ رکھے تو اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے ۔
۴۔ رمضان : روزہ اور قرآن کا مہینہ :
روزہ داری کے موضوع کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی صفات کو بھی خیار رکھنا چاہیے رمضان روزہ داروں کے لئے بہترین مہینہ ہے
اور بابرکت مہینہ ہے جو کہ مخصوص روزہ داروں کے لئے ہیں ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت ۸۵ میں آیا ہے ۔
اور رمضان کو کیوں رمضان کہتے ہیں اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں :إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها
۔ یعنی رمضان کو رمضان کہا جاتا کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے ۔
ماہ رمضان کی خصوصیات یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں : تورات چھٹی رمضان کو نازل ہوئی ہے انجیل بارہ رمضان کو اور زبور اٹھارہ رمضان کو اور قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا گیا ہے
تمام آسمانی کتابیں تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کے لئے رمضان کے مہینہ میں نازل ہوئی ہیں ۔ پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم نے شعبان کے مہینے کے آخری جمعہ کے خطبہ میں فرمایا : اے لوگو!خدا کا بابرکت مہینہ اور مغفرت اور رحمت کا مہینہ تمہاری طرف آرہا ہے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہیں اس مہینے کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں اس مہینے کی راتیں دوسرے مہینوں کے راتوں سے افضل ہیں اور اس مہینے کے تمام لحضات اور گھنٹے دوسرے مہینوں کے لحضات اور کھنٹوں سے افضل ہیں ۔
ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خدا وند عالم کی طرف سے تمہارے لئے دعوت ہوتی ہے اور ان لوگوں میں سے شمار ہوتے ہو کہ جنکو کو خدا وند عالم نے اکرام حسن کیا ہے تمہاری ہر سانس اس مہینے میں تسبیح شمار ہوتی ہے اور اگر اس مہینے میں سوجائے تو عبادت شمار ہوتی ہے اس مہینے میں تمہاری عبادات اور دعائیں قبول ہوں گی ۔
پس اپنے خدا سے خالص نیت اور پاک دلوں کے ساتھ خدا سے مانگو خدا وند عالم آپ کو اس مہینہ میں روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفسق دے ۔کیونکہ اس مغفرت والی مہینے سے کوئی شخص محروم ہو جائے تو وہ بدبخت ترین انسان شمار ہوتا ہے ۔
اس مہینے میں روزہ کی بھوک اور پیاس سے دوسرے فقیروں کی بھوک و پیاس کو یاد کریں اور فقیر و بیواؤں کا خیار رکھیں بوڑھوں کا احترام کریں اور ان پر رحم کریں اور صلہ رحمی کا خیال رکھیں اپنے خاندان اور رشتہ داوں کوآپس میں مضبوط کریں اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچائیں اور اپنی آنکھوں کو نامحرم سے بچا کر رکھیں اور ناجائز چیزوں کو سننے سے اپنی کانوں کو محفوظ رکھیں یتیموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آجائیں تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے ۔
یہ ماہ رمضان کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہوں اور فسادات میں کمی آجاتی ہے ۔
اس مہینہ میں قرآن نازل ہوا ہے اور شب قدر اسی مہینہ میں ہے ماہ رمضان کے ان تیس دنوں میں خدا کی معرفت اور اس کی طرف جانے کا راستہ فراہم ہو جاتا ہے اور انسان کو توبہ و ہدایت کا راستہ نصیب ہو گا باران رحمت بھی اسی مہینہ میں نازل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں بند کیا جاتا ہے ۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے :تُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَان
۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ۔
وَ قَد وَكَّلَ اللَّهُ بِكُلِ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ سَبْعَةً مِنْ مَلَائِكَتِهِ فَلَيْسَ بِمَحْلُولٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُكُمْ هَذَا
.
خدا وند متعال نے ہر شیطان پر ستر ملائکہ کو نگہبان قرار دیا ہے کہ شیطان میں یہ جرات نہ ہو کہ تمہارے اندر نقوذ کرے اور ماہ رمضان کے ختم ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آسکتا ہے ۔
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں توبہ اور اصلاح اور خدا کی طرف پلٹنے کا دروازہ کھلا ہے اور گناہ او رفساد کا دروازہ بند ہیں لیکن اگر انسان خود خدا کی رحمت سے بھاگنا چاہے تو یہ رحمت کے درواز ے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے ہیں اور جہنم کے دروازے اپنے او پر کھول دیے ہیں ۔
(راہی بسوی عافیت خیر می رود ---------- راہی بسوی ہاویہ اکنون مخیری )
یعنی ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ جہنم کی طرف جارہا ہے لیکن اختیار آپ کے پاس ہے کہ کس راستے کو اختیار کرنا ہے
تیسرا جزء : قیامت پر اعتقاد رکھنا :
(
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد
)
۔
۔ہمارے پروردگار! بلاشبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ۔
۱۔ قیامت میزان اعمال :
اس آیت میں علماء و مفکرین قیامت کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کو ہوا و ہوس اور بے مورد احساسات جو لغزش کا سبب بنتا ہے ان سے اپنے کو حفظ و امان میں رہے اور یہ وہی افراد ہیں جو انحرافات سے اپنے کو بچائے رکھا ہے ۔اسلام کی نگاہ میں انسان کو بغیر کسی مقصد و ہدف کے خلق نہیں کیا ہے بلکہ کسی ہدف اور مقصد کے لئے خلق کیا ہوا ہے پس ایک جگہ پر اس کے اعمال کی جانچ پڑتال کریں تاکہ جان لیں کہ اس نے کس حد تک اپنے اس ہدف و مقصد کو ثابت رکھا ہے اور اس دنیوی امتحان میں کتنا عمل صالح کو انجام دیا ہے
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكمُْ أَحْسَنُ عَمَلًا
)
اسی بنا پر قرآن مجید قیامت کو روز جزا و سزا کہہ کر ہمیں تعارف کراتا ہے
قیامت کے دن یا بہشت ہے یا جہنم ! جنہوں نے نیک اعمال بجالائیں اور عمل صالح انجام دیئے ان کے لئے بہشت ہو گی اور جنہوں نے برے اعمال انجام دیے ان کے لئے جہنم ہوگی ۔
خدا وند متعال ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسان کو تشویق دلاتا ہے اور ہوشیار کرتا ہے تاکہ انسان اپنے کو قیامت کے لئے تیار رکھے لذا قیامت دو جہتوں سے اثر تربیتی رکھتی ہے پہلا بہشت کا شوق اوردوسرا جہنم کا خوف
الف ۔ بہشت کا شوق :
جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیںمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشَّهَوَات
۔جو بھی جنت کا مشتاق ہے وہ شہوتوں سے ہاتھ اٹھائیں ۔
ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ پیغبمر اکرم صل اللہ و السلم حضرت فاطمہ کے پاس آئے دیکھا کہ گو د میں بچہ ہے اور اسکو دودھ پلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے آٹا پیسنے میں مصروف ہیں پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آئے فرمانے لگے بیٹی دنیا کی یہ مشکلات آخرت کی آسانی کی خاطر برداشت کریں چونکہ خدا وند متعال نے مجھ پر وحی بھیجا ہے کہ
(وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضى
) ۔
اور عنقریب آپ کا رب آپ کواتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
شوق بہشت کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات میں بیان ہوا ہے اور پیغمبر اکرم نے بھی اسی سے استفادہ کرتے ہوئے فرمارہا ہے :الجنة لها ثمانية أبواب فمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ
۔جنت کے آٹھ دروازے ہیں اگر کوئی ان آٹھ دروازوں سے داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ چار خصلتوں کو پالے ۔
۱۔ صدقہ ۔ عفو و درگزر ( بخشش ) حسن اخلاق لوگوں کو اذیت نہ دیں ۔ سورہ آل عمران کی آیت ۹ کے مطابق یہ ہے کہ خداوند متعال قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے ) یہ انسان فکر مند کے لئے ایک اہم اور تربیتی عامل ہو ۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا :کل قیامت کے دن بندہ ایک قدم آگے نہیں بڑھائے گا مگر ان سے چار چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائےگا ۔۱۔ عمر کو کہاں گزارا ؟ ۲۔جوانی کو کہاں صرف کیا ؟ ۳۔ مال کہاں سے لایا اور کہاں پر خرچ کیا ؟ ۴۔ اہل بیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ؟
بس جس انسان کو بہشت میں جانے کا شوق ہو تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی عمر کو اور اپنے مال ودولت کو اچھی طرح سے گزارے تاکہ اسے جنت نصیب ہو جائے ۔
ب ۔ جہنم کا خوف :
جہنم کا خوف انسان کو گناہوں اور فساد و تباہی اور دوسرے برے کاموں سے بچاتا ہے اس کے بارے میں بہت ساری آیات بیان ہوئی ہیں ۔
ایک دن امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا اور عرض کرنے لگا میں گنہگار ہوں آپ مجھے کوئی نصیحت کریں تاکہ مجھے گناہوں سے رہائی مل جائے تو امام علیہ السلام نے فرمایا : آپ صرف پانچ کام کریں پھر اس کے بعد جو کرنا ہےکرو !
۱۔ خدا کی دیے ہوئے رزق کو مت کھاو اور جو کرنا ہے گنا ہ کرو!
۲۔ خدا کی ولایت سے باہر نکلو اور جو بھی چاہے گناہ کرلو !
۳۔ ایسی جگہ پر جاو جہاں پر خدا نہ ہو اور جو چاہے گناہ کرلو !
۴۔ قبض روح کے لئے جو فرشتہ آتا ہے اس کو اپنے سے دور کرلو ! پھر جو چاہے گناہ کرلو !
۵۔ قیامت کے دن جہنم میں بھیجنے والا فرشتہ جب تمہیں کہیں کہ داخل ہو جاو تو تم داخل ہونے کے بعد جو بھی گناہ کرنا چاہتے ہو کرلو! ۔
۲۔ معاد اور قیامت کے بھول جانے کی دلیلیں :
معاد کو فراموش کرنا اصل میں بہت زیادہ گناہ اور طغیان کی وجہ سے ہیں
اسی حالت میں بندہ خدا کو زیادہ یاد کرے تو ذکر الہی کی وجہ سے انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے اور تقوا گناہوں سے دوری اور تہذیب نفس کی دلیل ہے ۔
قیامت کو بھول جانا اور اس کا انکار کرنے سے انسان کو اسی دنیا میں ہی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ۔
یہی وجہ ہے کہ خدا وندعالم نے قیامت کے بھولنے کو بد ترین اعمال میں سے جانا ہے
قیامت کے بھول جانے کی ایک اور دلیل قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ آزاد رہے اور کسی قید
و بند سے آزاد رہے مثل منطقی اور دینی امور سے آزاد رہنا چاہتاہے
۔
اس کے مقابل میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ :اجعل همک لمعادک تصلح
۔اپنی تمام اہتمام کو معاد کے لئے دے تاکہ معاد صحیح ہو جائیں ۔
بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو معاد اور قیامت کے بھول جانے کا سبب بنتے ہیں انہی میں سے کچھ درجہ ذیل ہیں ۔
الف ۔ لمبی آرزو کرنا :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو میں تم سے دو چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں اپنے نفس کی پیروی اور لمبی آرزو کرنے سے ۔ ہوای نفس کی پیروی کرنا تمہیں حق سے روک دیتا ہے اور لمبی آرزو کرنا تمہیں آخرت کو بھلا دینا ہے ۔
اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت حتمی ہے اور دنیا وآخرت میں سے ہر کسی کی اولاد ہیں پس آخرت کی اولاد ہونے کی کوشش کریں نہ کہ دنیا کی اولاد بنے ۔ چونکہ آخرت کے دن ہر کوئی اپنی ماں کے ساتھ ہوگا جس طرح کہ آج کا دن کام کرنے کا دن ہے حساب کادن نہیں اور کل قیامت کا دن حساب کا دن ہے نہ کہ اعمال کا دن
ب ۔ شہوت محوری :
امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے
:وَ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا فَقَدِ اسْتَهَزَأَ بِنَفْسِه
جو بھی جہنم کی آگ سے خد ا کی پنا ہ مانگیں اور شہوت دنیا کو ترک نہ کریں تو گویا اس نے اپنا مذاق اڈایا ہے ۔
پ ۔ دنیا شیفتگی :
(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَْيَوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الاَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
)
لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں
چوتھا جزء : غصہ پر کنٹرول کرنا :
(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَْيَوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الاَْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَالَّذِينَ يُنفِقُونَ فىِ السَّرَّاءِ وَ الضرََّّاءِ وَ الْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِين
)
(ان متقین کے لیے)جو خواہ آسودگی میں ہوں یا تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
۱۔ مدیریت خشم :
اس کے بعد کہ خدا وند متعال پرہیز گاروں کو بہشت جاودانی کا وعدہ دیا ہے کہ کی وسعت اور گنجائش تمام آسمان اور زمیں کے برابر ہے اس آیت میں پرہیز گاروں کی کچھ صفات بیان کرتا ہے ۔
۱۔ وسعت اور پریشانی کے وقت انفاق کرتے ہیں ۲۔ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور یہ نیکو کارلوگ ہیں کہ جن کو خدا وند متعال دوست رکھتاہے ۔
اس آیت میں مغفرت اور آمرزش کا وعدہ دینے کے بعد اگر کوئی بندہ خطا کرے اور خدا کو یاد کرتے ہوئے استغفار کرے تو خداوند متعال اس کو بخش دیتا ہے اور جو لوگ دوسروں کو بخش دیتے ہیں خدا وند بھی ان کو بخش دیتا ہے ۔
پرہیز گاروں کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے کظم غیظ ہے یعنی غصے کو پی جانا ۔ یہ اس وقت ہے جب کسی کو بہت ہی سخت غصہ آجائے اور اس کو کنٹرول کرے اور اس غصے پر قابو پالے وہ مراد ہے لیکن کوئی خداوند عالم کے لئے کسی کافر سے لڑنے میں یا کسی منافق کے ساتھ یا کسی گنہگار وغیرہ کے ساتھ غصہ کرنا مراد نہیں ہے
اگر غصہ پر کنٹرول نہ کرے تو اس کے بہت ہی خطرناک اثرات ہیں اور انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی بناپر غصہ پر کنٹرول کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے ۔جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ :أَعْظَمُ النَّاسِ سُلْطَاناً عَلَى نَفْسِهِ مَنْ قَمَعَ غَضَبَهُ وَ أَمَاتَ شَهْوَتَه
عظیم ترین انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور اپنی شہوت پر غالب آجائے ۔
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا غَضِبَ، لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ؛.
مؤمن کو اگر غصہ آجائے تو وہ حق سے باہرنہ نکلے یعنی آپے سے باہر نہ ہو ۔
۲۔ اعمال کے اثرات اور غصہ پر کنٹرول کرنا :
الف ) تیر شیطان کی نشانی :
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ والسلم کا فرمان ہے :الْغَضَبُ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَان
۔غصہ شیطان کا ایک شعلہ آور تیر ہے ۔
ب ) ایمان کو نابود کرنا :
غصہ ایمان کو سیلاب کی طرح نابود اور ویران کردیتا ہے غصہ کے وقت انسان اپنے آپ کو کھود یتا ہے اور کسی بھی چیز کا پابند نہیں رہتا ہے اور ہر گناہ میں مبتلا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا :الْغَضَبُ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ
.
غصہ ایمان کو خراب کردیتا ہے جس طرح سے شہد کڑوی دوائی کی اثرکو ختم کرتا ہے ۔
ت ) تمام برائیوں کی چابی :
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِ شَرٍّ
۔غصہ تمام برائیوں کی چابی ہے ۔
ث ) غصہ عقل کو خراب کرتی ہے :
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ :ايّاك و الغضب فأوّله جنون و آخره ندم
.
۔خبردار غصہ کرنے سے بچو کہ جس کا اول جنون ہے اور آخر میں شرمندگی ۔
ج )قتل و غارت :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے
أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِنَ الْغَضَبِ إِنَّ الرَّجُلَ يَغْضَبُ فَيَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ يَقْذِفُ الْمُحْصَنَة
۔ غصہ سے زیادہ بری چیز کونسی ہو سکتی ہے چونکہ غصہ میں انسان ایک دوسرے کو قتل کردیتا ہے اور نیک لوگوں کا گالیاں دیتا ہے ۔
اسی بنا پر غصہ کے دین اور دنیا دونوں پر منفی اثرات موجود ہیں لہذا انسان اپنے خشم و غصے کو کنٹرول میں رکھیں تو گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور ثواب کے اعتبار سے خداوند عالم اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے
غصہ پر کنٹرول کرنے والا انسان کل قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محشور ہوگا اور ان کا دل ایمان کے نور سے منور ہو گا
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ :اما الحلم
: لیکن حلم ان کے آثار میں سے ہیں ) اچھے کام انجام دینا اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اس کی شخصیت بڑائی ہونا اور پستی وغیرہ سے نکل جانا نیک کام کے بارے میں سوچنا اور بڑے مقام تک پہنچنا لوگوں کو قرض دینا اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو انسان حلم سے حاصل کرسکتا ہے ۔
۳۔ غصہ کے عوامل :
الف ) اپنے اوپر مسلط ہونا :
اپنے آپ پر مسلط ہونے کی تمرین کرنی چاہیے تاکہ اپنے آپ پر کنٹرول کرسکے جب انسان خود پر مسلط ہو جائے تو وہ اپنے خشم پر بھی کنٹرول کرسکتا ہے ۔
ب ) ہمت بلند :
نیک انسان جلدی اپنے آپ کو غصے کا اسیر نہیں بناتے ہیں اور آسانی کے ساتھ گناہ اور خطا کو انجام نہیں دیتے ہیں ۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے بردباری اور خونسردی ایک ہی باب کے دو بیٹے ہیں جو کہ بلند ہمتی سے حاصل ہوتے ہے ۔
پ ) معرفت اور توحید اور ایمان کی تقویت :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حلم چراغ الہی ہے جس کسی کےپاس بھی ہو وہ اس سے استفادہ کرتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو تا ہے انسان اس وقت تک حلیم نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے اند نور الہی نہ ہو اور اس کی معرفت نہ ہو
ت ) عقل کی تقویت :
امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ :ألحلم نور جوهره العقل
۔حلم ایک نور ہے اور اس کا جوہر عقل ہے ۔
ث ) قضاوت میں جلدی نہ کرنا :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ :من طبايع الجهّال التّسرّع إلى الغضب في كلّ حال
۔ جاہلوں کی طبیعت یہی ہے کہ وہ ہر حال میں غصہ اور خشم کی طرف جلدی کرتے ہیں ۔
ج ) تکبر اور خود بزرگ بینی سے دور رہنا :
جب حضرت عیسی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ غضب کا سرچشمہ کیا ہے ؟ تو فرمایا : َالْكِبْرُ وَ التَّجَبُّرُ وَ مَحْقَرَةُ النَّاسِ
.
۔ غضب کی ابتدا اور سرچسمہ کیا ہے ؟ تو فرمایا تکبر اور اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر جاننا ۔
چ ) حسد اور کینہ سے دور رہنا :
امام علی علیہ السلام نے فرمایا
:الْحِقْدُ مَثَارُ الْغَضَب
کینہ خشم کا سبب بنتا ہے ۔
ح ) حرص اور دنیا پرستی میں کمی آنا :
ہر وہ شخص جو دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو دوسری چیزیں اس کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس کا تمام ہم و غم سب کو اس دنیا کے لئے قربان کرتا ہے لذا اس پر غضب مسلط ہوتاہے لیکن اس کا ہدف اور مقصد اس دنیا کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتو اس کو جلدی غصہ نہیں آئے گا اسی وجہ سے حضرت عیسی نے غصہ کی دلیل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا :شدة الحرص على فضول المال
دنیا کی مال زیادہ ہونے پر لالچ رکھنا ۔
خ ) فقر کا کم ہونا :
بہت سارے موارد میں فقر و ناداری خشم و غضب کا سبب بنتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ فقر کی وجہ سے بچوں کو قتل کردینا ہے
۔اسی بنا پر اگر انسان کی زندگی میں اگر وسعت ہو تو اس خشم اور غضب میں کمی آجاتی ہے ۔
د ) خشم پر کنٹرول کرنے کا نتیجہ اور اخروی منافع پر توجہ دینا :
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اپنے خشم و غصہ پر کنٹرول کرتا ہے تو خداوند عالم دنیا و آخرت دونوں میں اس کو عزت عطا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ۔غصہ پر کنٹرول کرنے والے اور درگزر اور احسان کرنے والے کو خدا دوست رکھتاہے اور جتنا وہ غصہ کو پی لے گا اتنا ہی خدا اس کو بہشت میں جگہ عنایت کرے گا
س ) خدا کو یاد کرنا :
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے کہ اے آدم کے بیٹے غصہ کے وقت تم مجھے یاد کرو تاکہ میں اس وقت تمہیں یاد کروں گا اور جنکو میں نے ہلاک کرنا ہے ان کے ساتھ تمہیں ہلاک نہیں کرونگا۔
ش ) نصیحت خاص :
جتنے بھی موارد کو ذکر کیا ان کے علاوہ بھی درجہ ذیل موارد ہیں جو غصہ پر کنٹرول کرنے کے لئے مفید ہیں ۔
1۔أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
پڑھنا
/۲ ۔لاحول ولا قوة الا باللَّه العليّ العظيم
۳۔ سجدہ کرنا ۔۴ ۔ حالت کو بدل دینا یعنی اٹھ کر بیٹھ جانا ۵ ۔ وضو کرنا ۔
پانچواں جزء : حرام کھانے سے پرہیز کرنا :
(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَِرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيمًا
)
اے ایمان والو! تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو،بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے ۔
۱۔ باطل خوری کا معنی اور اہمیت :
اس آیت میں ایماندار لوگ مخاطب ہیں کہ وہ اپنے اموال کو ناجائز اور باطل طریقے سے نہ کھائیں اور عقل و منطق کے اعتبار سے دوسروں کے امول میں تصرف کرنے سے منع قرار دیاہے اور اس کو باطل قرار دیاہے جوکہ حق کے مقابل میں ہے ۔
قرآن کی بہت ساری جگہوں پر باایمان کو مخاطب قرار دیاہے اسی بنا پر ہر وہ کام جو تجاوز ارو دہوکہ و فریب پر مشتمل ہو اور ہروہ کام جس میں سود اور گناہ ہو ایسی چیزوں کو خرید و فروخت سب اسی آیت کی ضمن میں آتے ہیں ۔ لیکن ایسے معاملات جو طرفین کے رضایت پر مبنی ہو وہ باطل نہیں ہیں ۔
اور آخر میں خداوندمتعال نے خود کشی کو بھی حرام قرار دیا ہے خودکشی کے ساتھ اسکا رابطہ اس طرح سے ہے کہ اگر معاشرے میں معاملات صحیح انجام نہ پائے تو یہ معاشرہ خود کشی اور حرج ومرج کا شکار ہوتا ہے ۔ لذا اس آیت میں ہوشیار کررہا ہے کہ اگر ان دو قانون کی رعایت نہ کی جائے تو خدا کے قہر و غضب میں ہمیشہ جلتے رہیں گے
روایات میں بھی اس موضوع پر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے ۔ جیساکہ فرمایا :وَ قَالَ ع تَرْكُ لُقْمَةِ الْحَرَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ أَلْفَيْ رَكْعَةٍ تَطَوُّعاً
۔ حرام لقمہ کو ترک کرنا خدا کے نزدیک دو ہزار رکعت مستحب نماز سے زیادہ محبوب ہے۔
۲۔ حرام خوری کے آثار :
الف ) خداپرستی سے منحرف ہونا :
پیغمبر اکرم صل اللہ والسلم نے فرمایا :ان لكلّ أمّة عجل، و عجل هذه الأمّة الدّينار و الدّرهم
۔ہر دور کی امت کے لئے ایک گوسالہ ہے ( حضرت موسی کی قوم کیطرح دھوکہ کھاتے ہیں اور خدا پرستی سے خارج ہو جاتے ہیں ) اور اس دور کی امت کا گوسالہ درہم ودینار ہے ۔
ب ) فقر :
پیغمبر اکرم صل اللہ والسلم نے فرمایا:مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ أَفْقَرَهُ اللَّهُ
.
۔ جو بھی حرام مال کھائے گا تو خداوند اس کو فقیر بنا دے گا ۔
پ ) رو گردانی خدا :
پیغمبر اکرم صل اللہ والسلم نے فرمایا: جب انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ داخل ہو جاتا ہے تو جتنے بھی فرشتے آسمان اور زمیں پر ہے سب ہی اس پر لعنت بھیجتے ہیں ۔ اور جب تک وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں ہے تب تک خداوند عالم اس کی طرف نگاہ نہیں کرتاہے ۔
بس جو بھی حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس نے خدا کو ناراض کیا ہے اگر وہ شخص مرنے سے پہلے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا اور اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو جہنم اس کا ٹھکانا ہو گا ۔
و ) امام علی کی ولایت سے خارج ہونا :
امام علی علیہ السلام نے فرمایا :لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاما
.
کسی بھی مؤمن کے مال کو حرام کے طور پر کھائیں تو وہ ہمارے دوستوں میں سے نہیں ہے ۔
ت ) عبادت کا کوئی اثر نہ ہونا :
پیغمبر اکرم صل اللہ والسلم نے فرمایا :الْعِبَادَةُ مَعَ أَكْلِ الْحَرَامِ كَالْبِنَاءِ عَلَى الرَّمْل
حرام خوری کے ساتھ عبادت کرنا ریت پر گھر بنانے کی مانند ہے ۔
ث ) امر با المعروف اور نہی عن المنکر کا اثر نہ ہونا :
امام حسین علیہ السلام نے جتنی کوشش کی اور نہی عن المنکر کیا لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا
:فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِكُم
تمہارے پیٹ حرام سے بھر دیا گیا ہے اور تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ۔
۳۔ راہ نجات :
الف ) مال و دولت کا ابزار ہو نے کی طرف متوجہ ہونا :
(الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌْ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيرٌْ أَمَلا
)
مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگارکے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں۔
دنیا کی یہ مال و متاع انسان کے لئے امتحان و آزمائش ہیں یہ تو معاش زندگی اور خدا کی بندگی کا ایک آلہ ہے اسی لئے انسان کو زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ خدا کے مقابل میں قرار نہ پائے ۔
ب ) امانت خدا ہونے کی طرف متوجہ ہونا :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ۔ مال جو انسان کے پاس ہے وہ خداکی امانت ہے انسان کے پاس اسے امانت کے طور پر
رکھا گیا ہے اور خدا نے اس کو حکم دیا ہے کہ عام معمول کے مطابق کھایا پیا کریں یعنی عرف کے مطابق اپنا کھانا کپڑے اور دیگر
چیزوں میں رعایت کریں اور خوشی کریں سواری وغیرہ کو لے لیں اور اس سے جو بچ گیا اس کو اپنے مؤمن بھائی جوکہ نیازمند ہو ان کے درمیان میں تقسیم کریں اور اگر کوئی اس حد سے یعنی حد متعارف سے تجاوز کریں اور زیادہ ہی خرچ کریں تو گناہ اور اسراف ہے
چھٹا جزء : عدالت
(يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شهَُدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنََانُ قَوْمٍ عَلىَ أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لهَُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيم
)۔
اے ایمان والو! اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے، (ہر حال میں) عدل کرو! یہی تقویٰ کے قریب ترین ہے اور اللہ سے ڈرو، بےشک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
اللہ نے ایمان والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے ۔
۱۔ عادل بن جائیں :
یہ آیت مومنین کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے آپ خدا کے لئے قیام کریں اور حق و عدالت پر گواہی دیں ۔ عدالت سے منحرف ہونے والی عوامل میں سے ایک ( کینہ اور عداوت وغیرہ ) کو مورد توجہ دیتے ہوئے ان سے منع کررہا ہے اور اس کی وجہ عدالت کی زیادہ اہمیت ہونے کو بیان کرتی ہے ۔ عدالت کی اہمیت اس قدر ہے کہ پھر اسی پر اعتماد کرکے اسی پر گامزن رہنے کوبیان کرتا ہے اور تقوا کو اس کا قریبی فرض کرتا ہے یہاں پر گفتگو دشمنوں کے وجود کے بارےمیں ہے خدا وند عالم مومنین سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عدالت کے ساتھ گواہی دے دیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے گواہی دینا چھوڑ دے اور ایسا کرنا کینہ اور لاپر واہی کی وجہ سے ہے ۔
اور اسی طرح سے سورہ نساء آیت ۱۳۵ میں بھی عدالت سے منحرف ہونے کی دلیل کو کینہ اور افراطی بیان کیا ہے ۔
عدالت مسلمانوں کے درمیان مذہبی اصول میں سے ہیں اور خدا وند عالم کی صفات میں سے ایک ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہےبا العدل قامت السموات والارض
اسی عدالت کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم و استوار ہے ۔
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عدالت فقط اقتصادی ہی نہیں بلکہ چھوٹے امور میں بھی چاہیے سیاسی ہو فرہنگی ہو اور اخلاقی ہو سب میں جاری ہوتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے شرک کو عدالت سے خارج کیا ہے جیسا کہ فرمایا :
(إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم
)
۔ اور حدود الہی سے تجاوز کرنے والوں کے بارے میں
۔ اور کفر و بت پرستی اختیار کرنے کے بارےمیں ۔اور ( ما انزل اللہ ) کے مطابق حکم نہ کرنے والوں کے بارے میں
۔ اور کافر باپ اور بھائی کو دوست رکھنے
۔ کو ظلم قرار دیا ہے ۔
۲۔ موانع عدالت :
عدالت کا اہم ترین دشمن انسان کی ہوا و ہوس ہے جو دو چیزوں (دوستی افراطی اور دشمنی افراطی ) کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جیساکہ سورہ مائدہ آیت ۸ میں دشمنی افراطی اور سورہ نساء آیت ۱۳۵ میں دوستی افراطی کو عدالت کے مخالف ایک عامل جانا گیا ہے لیکن سورہ نساء کی ۱۳۵ ویں آیت میں ایک ایسے عامل کو بیان کرتاہے کہ جو دوستی اور بغض افراطی کا جڑ قرار دیا ہے یعنی ہوا و ہوس ہے جو ایسے عوامل کے مقابل میں قرار پایا ہے جو ہمیں عدالت کے لئے آمادہ کرتی ہیں ۔
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ۔ عدالت کے لئے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ کریں اور لالچ نہ کریں اور پرہیز گاری سے مدد لیں
۔
اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عدالت بعض امور ایک خاص جگہیں کا متحمل ہوتا ہے جیسا کہ کوئی اپنے خاص عہدے کی بنا پر اپنے کو بہت بڑا سمجھے اور سیاسی اور فرہنگی طاقتوں کو غلط استعمال کرے تو یہاں پر عدالت بہت خاص کام آتا ہے پیغمبر اکرم کا فرمان ہے سب سے پہلا وہ شخص جہنمی ہے جو لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے اور عدالت کا خیال نہیں رکھتاہے اور ایسا مالدار جو دوسروں کا حق نہیں دیتا اور ایسا فقیر جو اپنے فقر کو بیچ دیتا ہے
ابن یعفور کا کہنا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کسی مسلمان کی عدالت کیسے ثابت ہوگی ؟ تاکہ اس کی گواہی مانا جائے ؟ تو امام نے فرمایا : حیا اور پیٹ اور اپنی ہاتھ و زبان کو کنٹرول میں رکھا ہے اور گناہ کبیرہ جو کہ خدا نے جہنم کا وعدہ دیا ہے اس سے بچتا ہو تو اس کو پہچانا جائے گا شراب زنا اور عاق والدین اور جنگ سے فرار کرنا ان سے پرہیز کرتا ہو اور ان کو چھوڑنے کے لئے مدد کرتا ہو اور عیوب کو چھپاتا ہو تو مسلمانوں کو اس کی غیبت کرنا حرام ہے اور عدالت کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا واجب ہے ۔ اور پانچ وقت کی نمازوں کو خیال رکھتا ہو اور مسلمانوں کی نماز جماعت میں حاضر ہوت ہو تاکہ مسلمان مسجد اور جماعت سے روگردانی نہ کریں ۔ مگر یہ کہ کوئی دلیل ہو ۔۔۔ ؟
ساتواں جزء : دعا
(
قُلْ مَن يُنَجِّيكمُ مِّن ظُلُمَاتِ الْبرَِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضرَُّعًا وَ خُفْيَةً لَّئنِْ أَنجَئنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنهَْا وَ مِن كلُِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشرِْكُون)
کہدیجیے: کون ہے جو تمہیں صحراؤں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے ؟ جس سے تم گڑگڑا کر اور چپکے چپکے التجا کرتے ہو کہ اگر اس (بلا) سے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔کہدیجیے: تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔
۱۔ دعا تاریکی وحشت سے نجات :
خداوند متعال نے اس آیت میں مشرکین کی داخلی فطر ت کی طرف اشارہ کیا ہے اور چھپی ہوئی توحید کو دکھاتا ہے ۔
اس آیت میں اہم ترین نکات جو انسان کی مشکلات کے وقت دل کی گہرائیوں سے دعا کرے اور ان میں سے اہم ترین چیز خدا شناسی اور خدا کے وجود کے بارے میں توجہ دینا ہے انسان اپنی تمام مشکلات کے وقت شرک سے نکل کر تمام وجود کے ساتھ خداوند عالم کے سامنے آجاتے ہیں ۔
اور اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ راحت اور بے نیازی اہم ترین چیزیں ہیں جو انسان کو خد ا سے غافل کردیتی ہیں ایک لحظہ پہلے وہ خدا کے ساتھ تھا اور جیسا ہی اس کی مشکل حل ہوئی تو خدا سے غافل ہو جاتا ہے ۔ اوپر والی آیت میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ انسان مشکلات کے وقت خداوند عالم کے ساتھ متمسک رہتا ہے اور جب مشکلات ختم ہو جاتی تو تب بھی خدا کے
ساتھ رہنا چاہیے اور خداکو نہ بھولیں ۔ دوسری آیتوں میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ مشکلات اور گرفتاریاں ایک سبب ہے اس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ اپنے بند ے کی توجہ کو جلب کریں تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے
دعا کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ۔افضل العبادة الدعا
:
۔بہترین عبادت دعا ہے ۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :الدُّعَاءُ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآن
۔دعا کرنا قران پڑھنے سے زیادہ افضل ہے ۔
۱ ۔ دعا قبو ل ہونے والی عوامل :
الف ) ظلم سے دور رہنا :
امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خداوند عالم نے خود نہیں فرمایا ہے کہ آپ دعا کرو میں قبول کرونگا لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہیں تمام مظلوم اپنے پیروزی اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں انکی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور خدا ان کی مدد نہیں کرتاہے ؟
امام صادق نے فرمایا : افسوس ہو تم پر کوئی بھی اس کو یاد نہیں کرتا ہے مگر اس کی دعا خداوند عالم قبول کرتاہے لیکن ظالم کی دعا رد کرتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے
ب ) تلاش :
انسان کبھی کبھار تلاش و کوشش کو چھوڑ کر صرف دعاؤں میں لگ جاتے ہیں جبکہ دعا کرنا ان چیزوں کے لئے ہوتا ہے جو انسان کی تلاش و کوشش سے باہر ہو امام ہادی علیہ السلام کا فرمان ہے چار گروہ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ شخص جو گھر میں آرام سے بیٹھ کر دعا کرتا ہو کہ خدا یا مجھے روزی عطا کریں تو اس سے فرمایا جاتا ہے اے انسان ! کیا میں نے تم لوگوں کو سعی و تلاش کرنے کو نہیں کہا ہے
ب ) غفلت اور آلودگی سے پرہیز کرنا :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ۔لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ دُعَاءَ قَلْبلَاه
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ۔ مبادا تم میں سے کوئی خدا سے کوئی چیز مانگیں یہاں تک کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا بجا لائیں پھر
پیغمبر اور ان کی آل پر درود بیجھے اور اس کے بعد خدا کی درگاہ میں اپنی گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر دعا مانگیں
ت ) کام اور غذا کی طہارت :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ۔مَنْ أَحَبَ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْيُطَيِّبْ مَطْعَمَهُ وَ مَكْسَبَهُ
-
اگر کوئی چاہے اس کی دعا قبول ہو جائے تو اس کا کھانا اور کام کرنے کی جگہ پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے ۔
ث ) پیمان الہی پر عمل کرنا :
کسی نے امام علی علیہ السلام کے پاس آکر دعا کے قبول نہ ہونے کی شکایت کی تو امام نے فرمایا تمہاری فکر اور دل سات جگہوں پر خیانت کی ہے ۔
۱- خدا کو پہچانا ہے لیکن اس کے حق کو ادا نہیں کیا ہے اسی بنا پر اس خدا کو پہچاننے کا تمہارے لئے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ۔
۲- اس نے جو کچھ بھیجا ہے اس پر ایمان تو لایا ہے لیکن اس کی سنت کی مخالفت کی ہے تو تمہارے ایمان کا ثمرہ کیا ہے ؟
۳- کتاب الہی کو پڑھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا ہے کہا ہے کہ ہم نے سنا ہے اور اطاعت کریں گے لیکن مخالفت کی ہے
۴- کہتے ہو کہ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسے کاموں کو انجام دیتے ہو جو اس عذاب کے نزدیک ہوتے ہو۔
۵- کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے اس کو پسند کرتے ہو لیکن ایسا کام انجام دیتے ہو جو تمہیں اس ثواب سے دور کرتا ہے ۔
۶- خداوند عالم کی نعمت تو کھاتے ہو لیکن اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہو ۔
۷- آپ کو کہا گیا ہے کہ شیطان کے ساتھ دشمنی رکھو اس کا دعوا کرتے ہو لیکن عمل کے وقت شیطان کے ساتھ مخالفت نہیں کرتےہو ۔
۸- دوسروں کے عیب کو اپنے سامنے رکھتے ہو لیکن اپنے عیوب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو ۔
بس اسی حالت میں کس طرح کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تم کیوں انتظار کرتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں جبکہ تم نے خود اپنے لئے دروازہ بند کیا ہوا ہے لہذا تقوا اختیار کرو اور اپنے اعمال کو صحیح کرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں ۔
۳۔ دعا کے آثار :
دعا انسان کے زندگی میں بہت ہی مؤثر اور بابرکت ہوتی ہے ۔منجملہ ان میں سے
الف ) چاہتوں کا پورا ہو جانا :
(وقال ربکم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
).
۔ تم مجھے پکارو تاکہ تمہاری دعائیں مستجاب کروں ۔
ب ) قضاء الہی کا بدل جانا :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ۔لایرد القضاء الا الدعا ء
۔ یعنی قضاے الہی کو صرف دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے ۔
پ ) بلاؤں کا دفع ہونا :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے :ادفعوا ابواب البلاء با الدعاء
۔بلاؤں کے دروازے کو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بند کردو ۔
ت ) رحمت کا نازل ہونا :
امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے :الدعاء مفتاح الرحمة و مصباح الظلمة
دعا رحمت الہی کے لئے مفتاح اور اندھیری رات کے لئے چراغ ہے ۔
۴ آداب دعا :
الف ۔ بسم اللہ سے شروع کرنا :
پیغمبر اکرم ص کا فرمان ہے اس دعا کو خداوند عالم رد نہیں کرتا ہے جس کی ابتداء بسم اللہ سے ہوئی ہو ۔
ب ۔ ستایش خدا :
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :کل الدعا ء لایکون قبله تمجید فهو ابتر
۔
ہر وہ دعا جس میں خدا کی ستایش نہ ہو وہ ابتر ہے ۔
ت ۔ پیغمبر اور امام علی کو واسطہ قراردینا :
إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَكَ شَأْن
ا ۔ ۔
جب خدا سے کوئی حاجت طلب کرنا ہو تو کہیں خدایا بحق محمد و علی کے واسطے کہ جن کامرتبہ تیرے پاس بہت ہی بلند ہے ۔
ث ۔ نماز اور وضو :
امام صادق نے فرمایا : کوئی صحیح طریقے سے وضو کرے اور اور دو رکعت نماز پڑھے اور رکوع و سجود کو کامل کرے خدا و رسول کی حمد و ثنا کے بعد اپنی جاجت طلب کریں تو اس کی دعا قبول ہوجاتی ہے کوئی بھی شرعی حاجت ہو تو وہ ناامید نہیں ہوگا
ج ۔ مل کر دعاکرنا :
امام صادق نے فرمایا : کوئی بھی جگہ پر چار بندے مل کر دعا کریں تو ان کے وہاں سے جدا ہونے سے پہلے انکی دعا قبول ہو جاتی ہے
آٹھواں جزء : عبادت
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيرُْهُ إِنىِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم
)
ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پس انہوں نے کہا: اے قوم! تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
۱۔ توحید عبادی : شعار مشترک :
اس آیت میں بعض پیغمبروں کے بارےمیں ذکر ہوا ہے ان میں سے پہلا حضرت نوح کاذکر ہے جو لوگوں کو اسلام اور توحید خدا کی طرف دعوت دیتے تھے اور بت پرستی سے دور رہنے کی تبلیغ کرتے تھے ۔
تمام پیغمبروں کا یہی شعار تھا کہ خداوند عالم کی عبادت کرنے اور بت پرستی کو چھوڑنے کی تاکید کرتے تھے ۔
اسی وجہ سے اس سورہ میں بھی اسی شعار کو مختلف پیغمبروں نے تکرار کی ہے اور آیات ۶۵۔۷۳۔ ۸۵ میں اسی بنا پر بت پرستی کو پہلے زمانے سے اب تک انسان کی سعادت کے لئے مانع رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام ان کی فطرتوں کو بیدار کرنے کے بعد انکو بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہونے سے ڈرتا ہوں ۔ اور عبادت کی اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ خداوند متعال خود اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو عبادت کے خاطر خلق کیا ہے
(
وَ مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْانسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون
)
۔
۔اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔
اور اسی طرح سے خداوند متعال اماموں کی صفات کو عبادت قرار دیا ہے :(
وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيرَْاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَوةِ وَ إِيتَاءَ الزَّكَوةِ وَ كاَنُواْ لَنَا عَبِدِين
)
۔
اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق راہنمائی کرتے تھے اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی اور قیام نماز اور ادائیگی زکوۃ کے لیے ان کی طرف وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے
اور امام زمان علیہ السلام اس دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں :اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيَة
۔ خدایا تیری اطاعت کرنے اور گناہ سے دور رہنے کی ہمیں توفیق دے ۔
۲۔ بندگی کی اقسام :
امیر المؤمنین علی علیہ السلام عبادت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ
.
بعض لوگ خداکی عبادت کرتے ہیں بہشت میں داخل ہونے کے لئے اور یہ تاجروں والی عبادت ہے اور ایک گروہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کی خوف اور ڈر کی وجہ سے اور یہ غلاموں والی عبادت ہے ۔ اور تیسرا گروہ خدا کی شکر گزاری میں عبادت کرتے ہیں اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے جو بہترین عبادت ہے ۔
۳۔ بندگی کے شرائط :
الف ۔ یقین :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے :لا عبادة الا بیقین
۔عباد ت یقین کے ساتھ کی جاتی ہے ۔
ب ۔ خدا کو حاضر جاننا :
کوئی بھی حالت خدا سے مخفی نہیں ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ خدا کو حاضر سمجھ کر انجام دے زمین وآسمان میں جوبھی چیز موجود ہے سب سے خدا باخبر ہے کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے حتی کہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے بارےمیں بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور خدا کے علم میں ہے ۔
روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بہت ہی زیادہ گریہ کرتے تھے
پ ۔ شناخت رکھنا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ۔لا عبادة الا باالتفقه
۔ ماہر علم فقہ کے علاوہ کوئی عبادت ہی نہیں ہے ۔
۴۔ بندگی کے مصادیق :
الف۔ ملکوت کے بارےمیں فکر کرنا :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ملکوت آسمان اور زمین کے بارے میں فکر کرنا مخلصین کی عبادت ہے ۔
ب ۔ حلال کسب کرنا :
حدیث معراج میں خداوند متعال پیغمبر اسلام سے فرماتےہیں اے احمد ! بندگی کے دس اجزا ء ہیں اور ان میں سے نو /۹ جزء حلال کو طلب کرنا ہے جب آپ کی غذا پاک ہو گی تو آپ میرے حفظ و امان میں ہو
پ ۔ والدین اور امام و عالم کو دیکھنا :
عالم کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے اور امام عادل کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے اور دوستی خدا کی وجہ سے کسی کی طر ف دیکھنا عبادت ہے
ت۔ خدا پر حسن ظن رکھنا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ خدا پر حسن ظن رکھناخدا کی عبادت ہے ۔
۵۔ خدا کی بہترین بندگی :
روایات میں خدا کے بہترین بندوں کے کچھ نمونے بیان ہوئے ہیں ۔
خدا کے بارے میں علم و تواضع رکھنا ۔ اخلاص ۔ عفت ۔ اپنی عادت پر غلبہ پانا ۔ دنیا کی بے رغبتی ۔ فکر و اندیشہ اور فقہ ۔
نواں جزء :غفلت
(وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الجِْنِّ وَ الْانسِ لهَُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بهَِا وَ لهَُمْ أَعْينٌُ لَّا يُبْصِرُونَ بهَِا وَ لهَُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بهَِا أُوْلَئكَ كاَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئكَ هُمُ الْغَافِلُون
)
اور بتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو (گویا) جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہی لوگ تو (حق سے) غافل ہیں۔
۱۔ غافلوں کی سرنوشت :
اس آیت میں ایک گروہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہےکہ جو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں اور وہ غافل ہیں اور ان کے جہنمی ہونے کی وجہ انکی غفلت کو بیان کیا ہے اس غفلت کی وجہ سے وہ لوگ فکر نہیں کرتے اور آنکھ و کانوں کے نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ وہ ان سے عبرت نہیں لیتے ہیں غفلت انسان کو حیوان کے درجہ سے بھی پست کردیتی ہے چونکہ اگر حیوان غافل ہو جائے تو یہ انکی ذات اور فطرت میں ہے ۔
اس آیت میں جو اہم نکتہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کان آنکھ اور عقل سے استفادہ کرکے حقائق کو کشف نہیں کرتا اور خداوند عالم کا حکم ہے کہ جو ان چیزوں سے استفادہ نہ کرے تو وہ ظلممت اور تاریکی میں رے گا اور جہنم کا حقدار ہو گا ۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا وند عالم بہت سے جن و انس کو جہنم میں داخل کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ زبر دستی یا اجباری طور پر انکو جہنم میں ڈال دے گا بلکہ یہ خود انسان کی غفلت کی وجہ سے ہے کہ وہ جہنم کا حقدار ہوا ہے ۔
غفلت سے مراد خداوند عالم کی پروا نہ کرنا خدا کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل نہ کرنا واجبات کو ترک کرنا اور محرمات کو بجا لانا یہی وجہ ہے کہ اس غفلت کو گناہ کا مقدمہ جانا جاتا ہے ۔ خدا وند متعال پیغمبر اسلام کو ہوشیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
يَا أَحْمَدُ أَنْتَ لَا تَغْفُلُ أَبَداً مَنْ غَفَلَ عَنِّي لَا أُبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ
اے احمد ! آپ ہرگز مجھ سے غافل نہ ہونا اور جو مجھ سے غافل ہو جائے گا تو میں اس کی اعتنا ء نہیں کرونگا اور ہلاک ہوجائےگا ۔
پیغمبر اسلام نہ صرف اس بات کی طرف توجہ دیتے تھے بلکہ اپنی رسالت کے دور میں کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو اس غفلت سے دور رکھیں لذا امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ۔وَ يَتَتَبَّعُ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ
.
پیغمبر اسلام ایک ایسا ڈاکٹر ہے کہ لوگوں کے لئے غفلت کی دوائی تیار کرتا ہے اور اپنے غافل مریضوں کی طرف جاتا ہے ۔
۲۔ غفلت کیوں ہے ؟
الف ۔ غفلت سے بیدار رہنے والی چیزوں سے استفادہ نہ کرنا :
آیت کے مطابق بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فہم اور درک سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں اسی لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر غفلت سے بیدار ہونے والی چیزوں کو پیدا کرے۔
ب ۔ جہل :
خداوند عالم کی مقام و منزلت کو نہیں پہچاننا اور قیامت کی طرف توجہ نہ دینا اور اپنے اس مال و دولت کے ضائع ہونے سے غافل رہنا اورشیطان کے وسوسوں سے بے خبر ہونا یہ سارے غفلت کے اہم ترین عوامل میں سے ہیں انسان کو ان سے بچنا چاہیے ۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے : َإِنَّ مَنْ عَرَفَ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ
جو بھی اپنے روزگار کو جانتا ہے وہ کبھی بھی غفلت سے دور نہیں رہتا ہے ۔
ج ۔ نعمت کی مستی :
امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے انسان کی سنگدلی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے اور دنیا کی طرف رغبت اور مستی اور غرور و حاکمیت یہ ساری چیزیں انسان کو اچھے اعمال انجام دینے سے روک دیتی ہے اور خدا کو بھلا دیتی ہیں اور اس کو موت سے غافل کرتی ہے تاکہ وہ اس دنیا کی محبت میں غرق ہوجائیں اور خداکو بھول جائیں
ح ۔ لمبی آرزوئیں :
امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اےخدا کے بندے جان لو کہ لمبی آرزوئیں انسان کی عقل کو نابود وبرباد کرتی ہیں قیامت کو جھٹلاتی ہیں اور انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں اور آخراس کا انجام حسرت اور افسوس اسکو نصیب ہوا ہے ۔
۳۔ غفلت کا علاج :
قرآن کریم نے غفلت سے دوری کو عباد الرحمن کی ایک خصوصیت جانا ہے ۔
عباد الرحمن : سے مرادوہ لوگ ہیں جب قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو اندھے اور گونگے نہیں ہوتے بلکہ بیدار رہتے ہیں ۔
بعض چیزیں جو انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہیں :
الف ۔ خداکے حاضر و ناظر ہونے کی طرف متوجہ ہونا :
انسان اگر خدا سے غافل ہے تو خدا اس سے غافل نہیں کیونکہ خدا خود فرماتاہے کہ میں آپ کے شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں انسان اگر قرآن مجید کی ان نکتوں کی طرف توجہ دے دیں تو خدا کے سامنے شرمندہ اور غفلت سے بچ جائے گا ۔
(وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون
)
۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے ۔
اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں :بِدَوَامِ ذِكْرِ اللَّهِ تَنْجَابُ الْغَفْلَةُ
.
ہمیشہ یاد خدا غفلت سے نجات دیتی ہے ۔
ب ۔ نیک کام کی ہمت :
ایک دن پیغمبر اسلام نے ابوذر سے فرمایا :يَا أَبَا ذَرٍّ، هُمَ بِالْحَسَنَةِ، وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا، لِكَيْلَا تُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ
.
اچھے اور نیک کام کی نیت کرو اور اگر انجام نہ دے سکا تو بھی غافلوں میں سے شمار نہیں ہوگا ۔
ج ۔ محیط گناہ کو تغییر دینا :
دعائے ابو حمزہ ثمالی میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جب توفیق سلب ہو جائے تو اس طرح سے دعا کریں ۔
أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي آلِفَ مَجَالِسِ الْبَطَّالِينَ فَبَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ خَلَّيْتَنِي
یا مجھے غافلوں کی مجالس کا علاقہ مند دیکھا اور مجھے ان کے درمیان چھوڑ دیا
دسواں جزء : آبادی مسجد
(
مَا كاَنَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلىَ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فىِ النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتىَ الزَّكَوةَ وَ لَمْ يخَْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسىَ أُوْلَئكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِين)
مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ مساجد کو آباد کریں درحالیکہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان لوگوں کے اعمال برباد ہوگئے اوروہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی س نہیں ڈرتے ہیں ، پس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔
۱۔ مسجد لیاقت عمران :
مشرکین مکہ کے ساتھ جھاد کا حکم ہونے کے بعد بعض کہتے تھے کہ مشرکین کے بڑے اور بزرگوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے وہ مسجد الحرام میں حج کے مراسم کو ادا کرنے آئیں تاکہ مکہ آباد ہو جائے جاجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور مراسم حج بھی اچھی طریقے سے انجام پائے گا ۔
لیکن اوپر والی آیات نازل ہوئیں اور ان میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا کہ مشرکین کو حق حاصل نہیں کہ وہ مسجد کو آباد کریں کیونکہ انہوں نے کفر کا اعلان کیا ہے ۔ لیکن کیا ان کو منع کرنے کی دلیل یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے اور ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں اور خدا کے پا س ان کا کوئی مقام نہیں ہے اور ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے ۔
اس کے بعد مسجد کو آباد کرنے کے لئے پانچ شرائط بیان کرتاہے ۔
۱۔ خدا پر ایمان رکھنا ۲۔ قیامت پر ایمان رکھنا ۳۔ نماز قائم کرنا ۔ ۴۔ زکاۃ ادا کرنا ۔۵۔ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ۔
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہر جگہ پر عمل صالح کو ایمان کے پھل دار درخت جانتا ہے اور ہر عمل کا دارو مدار نیت اور عقیدے پر ہے اور ہمیشہ اسی کا رنگ لیتا ہے اور بری نیت سے کبھی بھی نیک اعمال انجام نہیں پاتے اور کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا ہے ۔
اور کلمہ ( لم یخش الا اللہ ) سےمعلوم ہوتاہے کہ مسجد کی آبادی اور عمران شجاعت اور شہامت کے علاوہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور یہ مقدس مراکز اس وقت انسان ساز بن سکتے ہیں کہ شجاع ترین محافظ اور خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والو ں کے ہاتھ میں ہو ۔ مسجد بنانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
مَنْ بَنَى مَسْجِداً كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ- بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّة
کوئی شخص ایک مسجد بنائے اگرچہ وہ مرغی کے گھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو خدا وند متعال بہشت میں اس کے لئے ایک گھر بنائے گا
لیکن ایک طرف سے اگر مسجد خالی پڑی رہے اس میں کوئی نماز پڑھنے نہ جائے تو قیامت کے دن یہ خدا کے حضور شکایت کرے گی جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے :تین چیزیں خدا کے ہاں شکایت کریں گی ۔
۱۔ خراب مسجد کہ جس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو ۔
۲۔ ایسا عالم جو نادانوں کے درمیان ہو ۔
۳۔ وہ قرآن جو طاقچہ میں پڑا رہے اور اس پر گرد و غبار پڑی ہو اور کوئی پڑھنے والا نہ ہو ۔
۳۔جو چیزیں مسجد میں ہونی چاہیے ۔
الف ۔ غیبت نہ ہو ۔
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے یہاں تک کہ کوئی حدث سرزد نہ ہو تو پوچھا گیا یارسول اللہ حدث کیا ہے ؟ تو فرمایا حدث سے مراد غیبت کرنا ہے
ب ۔ تین کام جو مسجد میں ہونے چاہیں :
پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجد میں فضول بیٹھنا منع ہے لیکن تین چیزوں کے لئے ۔ ۱ ۔ قرآن پڑھنے کے لئے ۲۔ خدا کی یاد کرنے کے لئے ۳۔اور علمی مباحثہ کرنا کے لئے :
پ ۔ ظلم نہ کرنا :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے خدا وند عالم نے مجھے وحی بیھجی : اے ڈرانے والے اپنی قوم کو ڈراو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں جبکہ خدا کے کسی بندے پر ستم کیا ہے جب یہ لوگ مسجد میں آکر میرے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں تو میں ان پر لعنت بھیج دونگا یہاں تک کہ وہ ظلم کو دور کردے اس صورت میں ان کے کان سنیں گے اور ان کی آنکھیں دیکھیں گی اور وہ اولیاء میں سے ہوجائیں گے اور قیامت کے دن شہدا اور صدیقین اور پیغمبروں کے ساتھ محشور ہونگے
ت ۔ مسجدمیں عفت کی رعایت کرنا :
عزاداری کے ایام میں مسجدوں میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ پیغمبر کے اس جملے میں بیان ہوئی ہیں کہ فرمایا :كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ.
مسجد کے اندر ناف ران اور زانو کو ظاہر کرنا عورت ( یعنی پوشیدہ رکھنا ) شمار ہوتا ہے ۔
۳۔ مسجد میں حاضر ہونے کے آثار :
الف ۔ آٹھ قسم کے آثار :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے جو بھی مسجد جانے کی عادت کرتا ہے اس کو آٹھ خصوصیات مل جاتی ہے ۔ استوار اور فریضہ کا انجام سنت قائم ہونا علم حاصل ہونا یا کوئی بھائی اس سے استفادہ کرے یا کوئی ایسا کلمہ جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرے یاکسی برے کام سے پلٹ جانا یا خداکی خوف سے یا حیا کی وجہ سے گناہ کو ترک کرنا ۔
ب۔ بہشت کو حاصل کرنا :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ۔من غدا الی المسجد او راح اعد الله له فی الجنة نزلا کلها غدا و راح
۔
جو بھی صبح کو یا رات کو مسجد میں جائے تو خداوند متعال اس کے لئے جنت کے دسترخوان آمادہ کرے گا ۔
ت ۔ عذاب میں تاخیر :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وقت اہل زمین میں سے کوئی نافرمانی کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو خداوند عالم ان کے گناہ کی وجہ سے غضب ناک ہو جاتا ہے اور بغیر استثنا ء کے عذاب کرنے کا سوچتا ہے اور پھر جب جوانوں کو مسجد میں دیکھتا ہے یا قرآن پڑھتے اورخدا کی یاد کرتے دیکھتا ہے تو سب پر رحم کرتا ہے اور عذاب سے بچاتا ہے اور ان سے عذاب کو دور کرتا ہے
ث ۔ گناہ کا کفارہ :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے جب کوئی بند ہ وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ آنے والے جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتاہے
گیارواں جزء : توبہ
(وَ ءَاخَرُونَ اعْترََفُواْ بِذُنُوبهِِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَ ءَاخَرَ سَيًِّا عَسىَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيهِْمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم
)
اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ، رحم کرنے والا ہے۔
۱۔ توبہ واپس پلٹنے کا راستہ :
روایت کے مطابق ( ابو البانہ انصاری ) اور کچھ افراد جو پیغمبر کے دوستوں میں سے تھے جنگ تبوک میں جانے سے انکار کیا تو ان کی مذمت میں آیت نازل ہوئی تو پیشمان ہوگئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھنے لگے جب پیغمبر اسلام مسجد تشریف لائے تو ان کو بتایا کہ انہوں نے قسم کھائی ہے جب تک تم لوگ جنگ سے واپس نہیں پلٹتے اسوقت تک خود کو آزاد نہیں کریں گے تو پیغمبر اسلام نے کہا میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ جب تک خدا کی طرف سے حکم نہیں آئے گا اسوقت تک انکو آزاد نہیں کرونگا اتنے میں آیت نازل ہوئی خدا وند عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے تو پبغمبر نے انکو آزاد کردیا ۔
اور انکی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اپنا سارا مال پیغمبر کے پاس لاکر پیش کیا اور کہنے لگے کہ یہ وہی مال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جنگ پر جانے سے انکار کیا تھا لذا آپ یہ مال ہم سے قبول کریں اور اسے خرچ کریں پیغمبر اسلام نے اسے قبول نہیں کیا تو آیت نازل ہوئی ۔
اور بعض روایات میں اسی آیت کے بارے میں داستان بنی قریظہ میں ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ تسلیم ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں مشورہ کیا اور انکو کہا کہ اگر تسلیم ہوگئے تو پیغمبر اسلام تمام کے سر تن سے جدا کردیں گے لیکن بعد میں پیشمان ہوئے اور توبہ کی
اس آیت میں وہ تمام افراد جنہوں نے اچھے کام انجام نہیں دیے ہے اور پیشمان ہوئے خدا نے ان سب کی توبہ قبول کی ہے اور اسی لئے اس آیت کو امید بخش ترین آیت سمجھا جاتا ہے ۔
اس آیت میں خدا نے توبہ کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو خدادوست رکھتاہے ۔
۲۔ توبہ قبول ہونے کی شرائط :
الف ۔ خدا سے دور نہیں ہونا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہےإِنَ اللَّهَ غَافِر َ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ علی اهله
.
خدا سب کے گناہوں کو معاف کردے گا لیکن شرط یہ ہے کہ خدا سے دور نہ ہوجائے جس طرح کہ اونٹ اپنے مالک کی ہاتھوں سے بھاگ جاتا ہے ۔
ب ۔ توبہ میں دیر نہ کرنا :
امام صادق علیہ اسلام سورہ نساء کی آیت ۱۸ کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ َذَاكَ إِذَا عَايَنَ أَمْرَ الْآخِرَة
۔انسا ن کے مرنے کے قریب جو توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی ۔
پ ۔ پیشمانی :
امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا :
من ندم فقد تاب من تاب فقد اناب
۔
جو پیشمان ہو جائے تو گویا اس نے توبہ کی اور جس نے توبہ کی گویا وہ پلٹ گیا ۔
ت ۔ اصلاح اور جبران :
اہم ترین چیز توبہ میں وہ اصلاح کرنا ہے پیغمبر اکرم کا فرمان ہے جب توبہ کرنے والے پر اس توبہ کا اثر نہ ہو ا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ صحیح نہیں ہے اس وقت تک دشمن کو راضی کرے نمازوں کو دوبارہ پڑھے اور تواضع کے ساتھ پیش آئیں اپنی شہوات پر کنٹرول کریں
ث۔ توبہ کے چھ معانی :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ۔ان الاستغفار درجة العليين و هو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى
استغفار انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے اور ایک ایسا نام ہے کہ جس کے چھ معانی ہے ان میں سے ایک اپنے گزشتہ اعمال پر شرمندہ ہونا ہے ۔
۱۔جو کچھ انجام دیا ہے اس پر پیشمان ہونا ۲۔ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ۔ ۳۔ لوگوں کے حقوق کوواپس کرنا ۔
۴۔ اپنی گردن پر جو واجبات ہیں انکو ادا کرنا ۔۵۔ حرام کھاکر بنی ہوئے بدن اور چربی کو پگھلا کر نیا خون اور گوشت آنے کا انتظار کرنا ۔۶۔ گناہ کی جو لذت حاصل کی ہے اس کے بدلےمیں رنج و غم کے ساتھ استغفار کرنا ۔
ج ۔گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ۔التَّوْبَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ دَعَائِمَ نَدَمٍ بِالْقَلْبِ وَ اسْتِغْفَارٍ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٍ بِالْجَوَارِحِ وَ عَزْمٍ أَنْ لَا يَعُودَ
توبہ کے چار ستون ہیں ۔ دل سے پیشمان ہونا زبان سے استغفار کرنا اعضاء بدن کا عمل کرنا گناہ سے بچنے کا ارادہ کرنا ۔
۳۔ انواع توبہ :
توبہ کی انواع و اقسام کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر گروہ کی ایک خاص توبہ ہوتا ہے ۔
پیغمبروں کی توبہ اضطراب اور سر ہے اور بزرگان کی توبہ اپنے نفس پر کنٹرول کرناہے اور اولیاء کی توبہ ذہن کے مختلف خطورات کو
پاک کرناہے اور توبہ خاص غیر خدا سے دوری کرنا ہے اور توبہ عام گناہ سے پرہیز کرنا ہے ۔
توبہ کی اقسام میں سے کچھ اس طرح سے ہیں گناہ کی قسم کو دیکھ کر کرنا ہے اگر گناہ بر سر عام ہے تو توبہ بھی عام ہونی چاہیے اور اگر گناہ چھپ کر انجام دیا ہوا ہے تو توبہ بھی چھپ کر کرنی ہے ۔
۴۔توبہ کے آثار :
انسان جب بہت سارے گناہ انجام دیتا ہے تو سمجھ لیتاہے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے اور کوئی راہ حل نہیں ہے تو اس وقت ہمارے لئے ایک ہی سہارا باقی رہتا ہے اور وہ توبہ کا سہارا ہے اور گزشتہ کئے ہوئے کا موں کی اصلاح کرنے کی فرصت مل جاتی ہے توبہ کے بعض آثار درجہ ذیل ہیں ۔
الف ۔ نزول رحمت :
امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں :
التَّوْبَةُ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ
.
۔ توبہ رحمت کو نازل کرتی ہے ۔
ب ۔ دل کا پاک ہونا :
امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ۔التَّوْبَةُ تُطَهِّرُ الْقُلُوبَ وَ تَغْسِلُ الذُّنُوب
.
توبہ دل کو پاک کرتا ہے اور گناہوں کودھو دیتا ہے ۔
پ ۔ گناہوں کو مٹا دیتا ہے :
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
:حُسْنُ التَّوْبَةِ يَمْحُو الْحَوْبَةَ
.
۔
توبہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے ۔
ت ۔ توبہ برے کو اچھے میں تبدیل کردیتی ہے :
(مَن تَابَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَِّاتِهِمْ حَسَنَات
)۔
جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جب قیامت کے دن مومن کو خداکے سامنے لایا جائےگا تاکہ اس کی تمام برائیوں کو آشکار کیا جائے یہ بندہ کہے کا میں جانتا ہوں کہ خداوند عالم فرماتا ہے دنیا میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے اور ابھی ان گناہوں کو معاف کرتاہوں اور میرے اس بندے کے سارے گناہوں کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل کردے اور اس کے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سبحان اللہ یعنی اس کے اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں تھا
بارواں جزء : شیطان شناسی
(إِلَّاإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَأَبَتِ إِنىِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتهُُمْ لىِ سَاجِدِينَ قَالَ يَابُنىََّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلىَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْانسَانِ عَدُوٌّ مُّبِين
)۔
جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا : اے بابا! میں نے(خواب میں )گیارہ ستاروں کو دیکھا ہے اور سور ج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
کہا : بیٹا ! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے .۔
۱۔ شیطان مشہور ترین دشمن :
قرآن مجید حضر ت یوسف کے قصے کو ان کے عجیب خواب سے شروع کرتاہے ایسا خواب کہ جو حضرت یوسف کی آدھی زندگی کو طلاطم میں ڈال دیا اور خواب میں سورج چاند اور ستارے انکو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے والد محتر م سے بیان کرتے ہیں ۔
ابن عباس سے نقل ہے کہ حضرت یوسف نے یہ خواب شب قدر اور شب جمعہ کو دیکھا اور ان کے والد یہ نہیں چاہتے تھے حضرت یوسف اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کرے چونکہ یہ انکا حسد کرنے کا امکان تھا ان کی اس سازش سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ایک خطرناک دشمن ہے ۔
شام بن حکم کا کہنا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے سوال کیاگیا کہ کس دشمن سے جہاد کرنا واجب ہے ؟ توفرمایا :أَقْرَبُهُمْ إِلَيْكَ وَ أَعْدَاهُمْ لَكَ وُ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ وَ هُوَ إِبْلِيسُ
.
تمہارے نزدیک ترین اور دشمن ترین جو تمہارے خلاف اکساتاہے وہ ابلیس ہے ۔
اسی دلیل کی وجہ سے ہیں کہ خدا وند عالم انسان کو ہوشیار رہنے کو کہتا ہے مبادا شیطان آپ کو دھوکہ دیگا جس طرح کہ تمہارے باپ دادا کو دھوکہ دے کر جنت سے نکال دیا ۔
۲۔ شیطان کیوں آزاد ہے :
یہ ایک سوال عمومی ہے کہ خدا نے کیوں شیطان کو خلق کیا ہے اور کیوں انسانوں کووسوسے میں ڈالتاہے ؟ خداوند متعال سورہ مبارکہ سباء میں ارشاد فرماتے ہیں ۔ اور ابلیس کو ان پر کوئی
بالادستی حاصل نہ تھی مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور ان میں سے کون اس بارے میں شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے
اسی بنا پر پہلا یہ کہ شیطان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتاہے اور نہ ہی کسی کو مجبور کرسکتاہے ۔(
وَ مَا كاَنَ لىَِ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنٍ
)
۔اور میرا تم پرکوئی زور نہیں چلتا تھا ۔
اور دوسرا یہ کہ شیطان صرف وسوسہ کرتاہے اور نافرمانی کی دعوت دیتاہے ۔(
وَ مَا كاَنَ لىَِ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لىِ
)
۔
۔اور میرا تم پرکوئی زور نہیں چلتا تھا۔ مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا ۔
تیسرا یہ کہ انسان اپنے اختیار سے شیطان کی دعوت کو قبول یا رد کرسکتاہے اور شیطان کی آزاد ہونے کی دلیل و سبب بھی یہی ہے کہ دعوت دیتا ہے اور انسان اپنے اختیار سے اسے قبول کرتاہے ۔(
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالاَْخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فىِ شَكٍ
ّ)
۔مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور ان میں سے کون اس بارے میں شک میں ہے ۔
چوتھا : یہ کہ خدا وند متعال ہر چیز کے بارے میں علم رکھتاہے اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے(
وَ رَبُّكَ عَلىَ كلُِّ شىَْءٍ حَفِيظ
)
اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے ۔
یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی حالت خود اس کو اور دوسروں کو معلوم ہوجائے تاکہ انسان پر کوئی حجت باقی نہ رہے ۔
پس ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر سے وسوسہ شیطانی کو دور کرے اور میدان عمل میں شیطان کو آشکار کرے اور اپنے دل میں خدا کا علم بٹھا دے تاکہ ثواب و عقاب کا مستحق ہو جائے لذا امام رضا علیہ السلام اس آیت
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا
)کی تفسیر میں فرماتے ہیں ۔
إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ لِيَبْلُوَهُمْ بِتَكْلِيفِ طَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الِامْتِحَانِ وَ التَّجْرِبَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلِيماً بِكُلِّ شَيْءٍ
.
خدا وند عالم نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے تاکہ ان کی عبادات اور اطاعت کے ذریعے سے ان کو آزمائیں نہ کہ صرف تجربہ اور امتحان کی خاطر چونکہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے ۔
۳۔ شیطان کا ہتھیار :
شیطان کے اہم ترین ہتھیار درجہ ذیل ہیں ۔
الف ۔ وسوسہ :
شیطان کی اہم ہتھیار انسان کو فریب دینے کے لئے وسوسہ ہے مختلف احساسات ( غضب شہوت اور وہم وغیرہ ۔۔) کو انسان کے اندر پیدا کرتاہے اور اپنی کامیابی کے لئے اس کو تیار کرکے رکھتا ہے ۔ اسی لئے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ :
إحذروا عدوّا نفذ في الصّدور خفيّا و نفث في الأذان نجيّا
.
دشمن سے دوری اختیار کریں چونکہ وہ تمہارے چھپے ہوئے دل میں داخل ہوجاتا ہے اور کانوں میں پھونکتا ہے ۔
ب۔ عورت ، شراب اور دولت :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہالْفِتَنُ ثَلَاثٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَيْفُ الشَّيْطَانِ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّيْطَانِ وَ حُبُّ الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّيْطَان
تین قسم کا فتنہ ہے حرام راستے سے عورت کے ساتھ محبت کرنا اور یہ شیطان کی تلوار ہے اور شراب پینا اور یہ شیطان کی جال ہے اور دینار و درہم سے محبت کرنا یہ شیطان کا تیر ہے ۔
پ ۔ شیطان کے مخالف عمل کرنا :
(وَ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
)۔
اس آیت کی ذیل میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
كُلُ يَمِينٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فَهِيَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
.
۔ہر وہ قسم جو غیر خدا کے لئے ہو وہ شیطان کے راستے ہیں ۔
ت ۔ گنہگاروں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے َمُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَى مَنْسَاةٌ لِلْإِيمَانِ وَ مَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ
۔اہل ہوس کے ساتھ بیٹھنا ایمان کو بھول جانے کا اور شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے ۔
امیر المؤمنین سورہ اعراف کی آیت ۱۶ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو خبر دار کرت ہیں اور کچھ گروہ کو شیطان کی تصدیق کرنے والے جانتے ہیں
صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ الْحَمِيَّةِ وَ إِخْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ وَ فُرْسَانُ الْكِبْرِ وَ الْجَاهِلِيَّة
.
۔
خود پسند اور متعصب لوگ اور خود خواہی اور خود پرستی اور جاہل لوگ شیطان کی تصدیق کرتے ہیں ۔
۴۔ شیطان سے کیسے بھاگنا چاہیے؟
جس طرح سے انسان کو خراب کرنے کے لئے شیطان کے پاس مختلف آلات موجود ہیں اسی طرح سے انسان کے پاس بھی اپنے دفاع کے لئے اسلحہ موجود ہے اسی لئے شیطان کا مکر بہت ہی ضعیف ہے ۔
۱لف ۔ آگاہی حیات بخش :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے :ستكون فتن يصبح الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا إلّا من أحياه اللَّه بالعلم
.
۔
عنقریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ لوگ صبح کو مؤمن اور اور شام تک کافر ہو جائیں گے مگر یہ خدا وند متعال علم کے ذریعے سے انکو زندہ کرے گا ۔
ب ۔ استغفار :
اس اسلحہ کے ذریعے سے انسان گناہ سے بچ جاتے ہیں اور ناامیدی سے جو گناہ ہو تے ہیں ان سے رک جاتے ہیں اسی لئے شیطان اپنی تمام قوت کے ساتھ کوشش کرتاہے کہ انسان استغفار نہ کرے ۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت (افعلو فاحشة
) نازل ہوئی تو شیطان مکہ میں ایک پہاڑ پر چڑھ کر فریاد کرنے لگا یہاں تک کہ عفریت میں سے ایک وسواس خناس نام کا تھا اس نے کہا :
َ أَعِدُهُمْ وَ أُمَنِّيهِمْ حَتَّى يُوَاقِعُوا الْخَطِيئَةَ فَإِذَا وَاقَعُوا الْخَطِيئَةَ أَنْسَيْتُهُمُ الِاسْتِغْفَارَ
ان کو وعدہ دونگا اور امیدوار کرونگا تاکہ وہ گناہ کریں اور استغفار کرنے سے بھلا دونگا ۔تو شیطان نے اس سے کہا کہ اس کام کی ذمہ داری آپ کی ہو گی ۔
پ ۔ پانچ مطمئن طریقے :
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : شیطان کا کہنا ہے کہ پانچ افراد کو بہکانے کے لئے میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے باقی سب میرے ہاتھ میں ہیں ۔
ایسا بندہ جو صدق نیت کے ساتھ خدا سے متمسک ہوتا ہے اور ہر کام کے لئے خدا پر توکل کرتا ہے ۔
اور جو دن رات خدا کی تسبیح و تہلیل کرتاہے ۔
اور جو چیز اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے مؤمن بھائی کے لئے پسند کرے ۔
اور جو مصیبت کے وقت جزع نہیں کرتا ہے ۔ اور جو کچھ خدا نے اسے عطا کیا ہے اسی پر راضی ہو جاتاہے اور اپنی پوری زندگی صرف روزی حاصل کرنے میں نہیں گزارتا ہے ۔
ت ۔ خداسے حقیقی ڈرنا :
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ۔ َ
تَحَرَّزْ مِنْ إِبْلِيسَ بِالْخَوْفِ الصَّادِق
۔
خداوند عالم سے حقیقی ڈرو تاکہ شیطان کے جال سے بچو ۔
ث ۔ زیادہ دعا کرنا :
امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
أَكْثِرِ الدُّعَاءَ تَسْلَمْ مِنْ سَوْرَةِ الشَّيْطَانِ
۔زیادہ دعا کرو تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو ۔
ج ۔ روزہ اور صدقہ ۔۔ :
پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا اگر چاہتے ہو تو ایک ایسی چیز تمہیں بتا دوں کہ شیطان تم سے مشرق اور مغرب کے فاصلہ پر دور ہو جائے تو سب نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے تو فرمایا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کردیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ۔ اور استغفار شیطان کے دل کی رگوں کو پھاڑ دیتا ہے
چ ۔ توجہ نہ کرنا:
امام صادق علیہ اسلام اعمال میں توجہ اور مبالات کو ضروری سمجھتے ہیں اور معتقد ہیں کہ اگر انسان بے توجہی کو ظاہر کریں تو وہ شیطان کا نوالہ بن جاتا ہے
۔
ح ۔ شخصیت پرستی سے بچنا :
امیر المؤمنین لوگوں سے چاہتے ہیں کہ برے اور فریب کا ر لوگوں سے بچو ! اور فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہو اپنے بزرگوں کی پیروی کرنے سے کیونکہ وہ لوگ اپنے حسب ونسب پر ناز کرتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں اور برے کاموں کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں اور شیطان انہی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کے ذہنوں کو خراب کرکے اپنے تیر کا نشانہ بناتا ہے اور تمہاری ثابت قدمی کو وسوسہ کرتاہے
آگاہ ہو جاو اپنے ان بزرگوں اور سرداروں کی اطاعت کرنے سے محتاط رہو جنہوں نے اپنے حسب اور نسب کی بنیاد پر اپنے کو بڑا سمجھا اور بدنما چیزوں کو خدا کے سر پر ڈال دیا اور اس کا انکار کردیا ۔
یہی وہ لوگ ہیں جو عصبیت کی بنیاد پر فتنہ اور جاہلیت کا سبب بن گئے ۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو اور ان کے جھوٹے مدعیان کی اطاعت نہ کرو جن کے گندے پانی کے اپنے صاف پانی سے ملا کر پی رہے ہو اور جن کی بیماری کو تم نے اپنی صحت کے ساتھ مخلوط کردیاہے اور جن کے باطل کو اپنے حق میں ملا دیا ہے یہ لوگ فسق و فجور کی بنیادیں اور نافرمانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ابلیس نے انہیں گمراہی کی سواری بنادیاہے ۔
اور ایسا لشکر قرار دیاہے جس کے ذریعے سے لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور یہی اس کے ترجمان ہیں کہ جن کی زبان کے ذریعے سے بولتاہے اور تمہیں اپنے تیروں کا نشانہ اور اپنے ہاتھوں کا کھلونہ بنایا ہے ۔
تیرواں جزء : خدا کی رحمت سے نا امید ہو نا :
(يَبَنىَِّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لَا تَاْيَْسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَاْيَْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُون
)
اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔
۱۔ نا امید نہیں ہونا :
نا امیدی سے مراد انسان بے کس و بے یار و مددگا ر ہے مایوس انسان اپنے آپ کو پہاڑ جیسا مشکل اور تنہائی کا احساس کرتا ہے اور کوئی اس کو مدد کرنے والا نظر نہیں آتا او راپنے نفس کا اسیر ہو تا ہے یہی وجہ ہے کہ ناامیدی کو شیطانی کا م اور کفر کے عوامل میں جانا جاتا ہے ۔
قرآن مجید حضرت یوسف کے گم ہونے کا واقعہ اور ان کے والد کے تلاش کرنے کے بعد ان کی ملاقات کو بیان کرتا ہے ۔
مصر اور اس کے اطراف میں قحط سے دوچار ہوتے تھے من جملہ انہی میں سے کنعان میں بھی قحطی آگئی حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو گندم لینے کے لئے مصر بھیجا ۔
۲۔ ناامیدی گناہ کا ریشہ ہے :
اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو یہ اطمینان حاصل تھا کہ یوسف ملنے والا نہیں ہے او راس کے تلاش کرنے میں ناامید تھے اسی وجہ سے حضرت یعقو ب ان کو بار بارتاکید کرتے تھے کہ
(إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ
)۔
اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔
اسی وجہ سے کافر اپنے آپ کو بہت ہی بڑی مشکل میں پاتے ہیں اور انکی اس ناامیدی کے وجہ سے انکو کوئی مدد کرنے والا نظر
نہیں آتا ہے یہی وہ اہم ترین نکتہ ہے جو ان کو انحراف کی طر ف لیجاتا ہے اور گناہ کی شکل اپناتے ہیں چونکہ گناہوں کی بنیاد خدا سے نا امیدی ہے ۔
جیسا کہ ہم روایت میں پڑھتے ہیں کہ :إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ الْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
..
۔
خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ نا امیدی ہے ۔ گناہ کی دلیل ناامیدی ہے
۱ ۔ جب تک امید ہے بخشنے کی امید ہے اور اصلاح و امید اور توبہ ہے اسی وجہ سے شیطان صفت انسان کا اہم کام یہ ہے کہ وہ امید کو گناہ کاران کے دل سے نکالتے ہیں تاکہ دوبارہ توبہ کی طرف پلٹ نہ جائے ۔
ناامیدی سے انسان کا رابطہ خدا سے قطع ہو جاتا ہے اور شیطان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے ۔
۲۔ نا امید انسان کو بخشش کی امید نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اصلاح کی طرف نہیں دیکھتا ہیں اور آہستہ آہستہ غلط راستے پر گامزن ہو جاتا ہے پھر سمجھ جاتا ہے کہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اسی راستے پر ہی رہتے ہیں اور امید کا کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا ۔
لیکن امید وار انسان صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ امید کے راستے پر گامزن رہتے ہیں اور اس طرح سے صبر کرنے والوں کو خدا وند متعال نے قرآن مجید میں خوش خبری دی ہے کہ : ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات (کے نقصانات) سے ضرور آزمائیں گے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔
۳۔ نا امیدی کا علاج :
نا امیدی کے علا ج کے لئے اہم ترین نکتہ وہی حضر ت یعقوب علیہ السلام کی تاکید ہے کہ فرمایا تھا خدا پر ایمان رکھنا اور کفر اختیار نہیں کرنا خدا کی قدرت ہماری سوچ اور فکر سے اوپر ہے اور بے نہایت ہے پس جان لینا چاہیے کہ جتنی بھی بڑی مشکل ہو وہ خدا وند عالم کی ذات سے بالا تر نہیں بلکہ خدا کی ذات اس سے بلند و بالا اور بے نہایت بڑا ہے ۔
انسان ایمان کے ساتھ جانتے ہیں ۔
الف ۔ خدا کی رحمت ہر موجودات سے بالا تر ہے
۔ (وَ رَحْمَتىِ وَسِعَتْ كلَُّ شىَْء
)
ب ۔ اہل تقوا پر خدا کی رحمت خاص ہوتی ہے فرمایا
: (وَ رَحْمَتىِ وَسِعَتْ كلَُّ شىَْءٍ فَسَأَكْتُبهَُا لِلَّذِينَ يَتَّقُون
)
ج ۔ نیک کام کرنے والا انسان بھی رحمت کے خاص دائرے میں شامل ہوتا ہے
: (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِين
)
د ۔ خدا وند عالم رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے
: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
).
تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے ۔
ھ ۔ خدا کی رحمت کے لئے کوئی مانع نہیں بن سکتاہے
: (مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا
)
لوگوں کے لیے جو رحمت (کا دروازہ) اللہ کھولے اسے کوئی روکنے والا نہیں ۔
و خدا کی رحمت گناہ کے لئے مانع بنتی ہے
: (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبىِّ
)
نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے ۔
اگر انسان خداکی رحمت کو قبول کرے اور اور اس کے اوپر یقین رکھے تو وہ ہرگز ناامید نہیں ہوگا اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام تاکید کرتے ہیں کہ صرف کافر ہی جو خداکی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں ۔
خداوند متعال سورہ زمر کی آیت /۵۳ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اس میں دو دلیل بیان کرتاہے ۔ پہلا غفار الذنوب ۔ خدا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ۔
اور دوسرا خداوند عالم رحیم اور مہربان ہے ۔ لذا کوئی بھی خداکی رحمت سے ناامید ہو جاتاہے تو ان دو دلیلوں کی وجہ سے امید اور رحمت الہی تک پہنچ سکتاہے انسان کے پاس وقت ہے جب تک خدا ہے تب تک زندگی گزارنا ہے ۔
چودواں جزء : احسان :
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَنِ وَ إِيتَاى ذِى الْقُرْبىَ وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون
)
یقینا اللہ عدل اور احسان اور قرابتداروں کو (ان کا حق) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحت قبول کرو۔
۱۔احسان یعنی نیکی کرنا :
اس آیت میں چھ اہم چیزوں کے بارے میں متوجہ کرایاہے ۔
خداوند متعال نے سب سے پہلے اپنے عزیز وں کے ساتھ عدل و احسان اور بخشش کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیاہے ۔
عدل یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھناہے اور ہر قسم کے انحرافات اور افراط و تفریط اس کے خلاف ہے لیکن فقط عدالت سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس سے ایک مرحلہ اوپر احسان کرنے کا بھی حکم ہوا ہے اسی وجہ سے تمام مشکلات کا حل صرف عدالت سے ہی ممکن نہیں بلکہ عفو و درگزر اور فداکاری بھی ہونی چاہیے کہ جس کو احسان کا نام دیا گیا ہے اصل میں معاشرے کے اندر عدالت اور احسان دونوں ہی کی ضرورت ہے ۔
امام علی علیہ السلام کافرمان ہے ِالْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّل
آیہ کریمہ میں عدل وانصاف اور احسان سے مراد فضل و کرم ہے ۔
یہ آیت قرآن مجید میں جامع ترین آیت ہے اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا :جماع التقوی من قوله تعالی إِنَ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان
.
تقوا کا مجموعہ ان کلمات میں ہے کہ خداوند عالم نے عدل و احسان کا حکم دیا ۔
اور اس آیت(
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
)
میں مفسروں کا بیان ہے کہ احسان نیکی کو کہا جاتاہے لیکن کبھی کبھار عمل صالح اور اچھے کا م کو بھی کہا جاتا ہے اسی لئے پیغمبر اسلام اس احسان کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُفَإِنَّهُ يَرَاك
خداکی اس طرح سے عبادت کرو کہ جیسا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ۔
احسان کی ارز ش اور اہمیت کے بارے میں معصومین کی راوایات میں بیان ہوا ہے جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ۔
الْإِحْسَانُ غَرِيزَةُ الْأَخْيَارِ وَ الْإِسَائَةُ غَرِيزَةُ الْأَشْرَارِ
.
۔ احسان نیکیوں کا اور شر بدیوں کا سرچشمہ ہے ۔
۲۔ احسان کے آثار :
الف ۔ گناہ سے چشم پوشی کرنا:
بالإحسان تغمد الذّنوب
۔احسان کے ذریعے گناہوں سے دوری ہو سکتی ہے ۔
ب ۔ دوست اور محبت دائمی :
مَنْ كَثُرَ إِحْسَانُهُ أَحَبَّهُ إِخْوَانُهُ.
۔ جس کی بھی نیکیاں زیادہ ہو ں لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ۔
پ ۔ دلوں کا مالک :
بِالْإِحْسَانِ تُمْلَكُ الْقُلُوبُ
.
۔احسان کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جاتا ہے ۔
ت ۔ اپنے آپ سے نیکی کرنا :
(إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكمُْ وَ إِنْ أَسَأْتمُْ فَلَهَا
)۔
اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی اور اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے حق میں کی ۔
ث ۔ دنیوی نتیجہ :
(لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فىِ هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَارُ الاَْخِرَةِ خَيرٌْ
)۔
بہترین چیز، نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ۔
احسان اگر کوئی مشرک اور غیر مسلم کے لئے بھی ہو تو وہ دنیا میں اثرانداز ہے ۔لذا ایک دن عدی بن حاتم پیغمبر کے پاس آئے تو پیغمبر نے ان کے والد کے بارےمیں فرمایا:ان اباک اراد امرا فادرکه یعنی الذکر
تمہارے والد جو چاہ رہے تھے وہ حاصل کیا یعنی دنیا میں اس کا ذکر ۔
پندرواں جزء : نماز شب و شب زندہ داری
(وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسىَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محَّْمُودًا
)۔
۔
اوررات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو، یہ ایک زائد (عمل) صرف آپ کے لیے ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. ۔
۱۔ مقام محمود : میوہ نماز شب :
خداوند عالم اس آیت میں پیغمبر اسلام کو مخاطب قرار دےکر کہہ رہے ہیں آپ آدھی رات کو نیند سے اٹھے اور نماز و قرآن کو پڑھے یہ ایک اضافہ وظیفہ شمار ہوگا تاکہ تم مقام محمود تک پہنچ جائےگا ۔
مفسرین کے نزدیک
(وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ
)سے مراد نماز شب ادا کرناہے
تھجد اصل میں ھجود کے مادہ سے ہے جو نیند کے معنی میں اور اس کا الٹا معنی بیداری کا ہوتا ہے ۔ اور نافلۃ سے مراد اضافی چیز کو کہا جاتاہے اس آیت سے کی ظاہرہوتاہے کہ نماز شب پیغمبر پر واجب تھی ۔
اور اس آیت میں نماز شب کے ذیل میں بیان کرتاہے اور مقام محمود کا اثر نماز شب کو قرار دیا ہے ۔ اور بعض مفسرین کے نظریے کے مطابق اس مقام سےمراد آخر میں پیغمبر اکرم کی شفاعت مراد ہے ۔اور بعض کے نظریے کے مطابق یہ مقام محمود سےمراد تقرب الی اللہ ہے ۔پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ آدھی رات کو دو رکعت نماز پڑھنا میرےلئے تمام دینا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے افضل ہے
۲۔ نماز شب کے آثار :
الف ۔ خداکے ساتھ دوستی :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو اطعام اور آدھی رات کو نماز شب پڑھنے کی وجہ سے ان کو انتخاب کیا تھا
ب ۔ افتخار مؤمن :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے مؤمن کی شرافت اس کی نماز شب پڑھنے میں ہے اور اس کی عزت لوگوں کو اذیت نہ دینے میں ہے
پ ۔ بخشش الہی :
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے : جب انسان اپنی نیند کی لذت چھوڑ کر نماز پڑھنے کو اٹھتاہے تاکہ اپنے اس پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرے تو خداوند عالم اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا آپ میرے بندے کو نہیں دیکھتے جو اپنی پیاری نیند کو خراب کرکے میری خاطر اٹھتا ہے جبکہ یہ نماز اس پر واجب بھی نہیں ہے آپ گواہ رہنا کہ میں نے انکو بخش دیا ہے ۔
ت ۔ بدن کی سلامتی :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کےوقت اٹھنا انسان کی بدن کی سلامتی کا سبب بنتاہے اور خدا کی خوشنودی کا سبب بنتاہے اور رحمت کا سبب بنتاہے اور یہ پیغمبروں کے اخلاق میں سے شمار ہوتا ہے
ج ۔ چہرے کا نورانی ہونا :
امام صادق کا فرمان ہے : نماز شب انسان کو خوش اخلاق بناتاہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اس کا غم دور ہوتا ہے اور
چہرے کو نورانی کرتاہے
۳۔ نماز شب کے موانع :
نماز شب توفیق الہی کو طلب کرتی ہے اس کے سایہ میں گناہ کا ترک کرنا انسان کو ممکن ہوتاہے ۔ امام علی کے پاس ایک شخص آکر کہنے لگا اے امیر المؤمنین میں نماز شب پڑھنے سے محروم ہوں ؟ توفرمایا : تم ایسے شخص ہو کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہے
اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : انسان گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے نماز شب سے محروم رہتے ہیں جسطرح کہ برا کام چاقو سے بھی تیز اپنے صاحب پر اثر کرتاہے
اور پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص آدھی رات کو اٹھ کر نماز شب پڑھنے کی نیت کرکے سوجائے اور نیند کے غلبہ سے اٹھ نہ سکے تو اس کی نیند صدقہ شمار ہوگی اور جس نیت کے ساتھ سویا تھا اس نیت کا ثواب خدا اسے عنایت کرےگا
سولواں جزء : نماز :
(وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَ اصْطَبرِْ عَلَيهَْا لَا نَسَْلُكَ رِزْقًا نحَّْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى
)۔
اوراپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ آپ کو رزق ہم دیتے ہیں اور انجام اہل تقویٰ ہی کے لیے ہے۔
۱۔ نماز کی اہمیت :
اس آیت میں خداوند متعال پیغمبر اسلام سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اہل عیال کو اس نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز قائم کریں چونکہ نماز دل کی صفائی اور پاکیزگی کا باعث بنتا ہے اور خدا کی یاد کو اضافہ کرتاہے ۔ نماز کا فائدہ خود تمہاری طرف ہی پلٹ جاتا ہے اور خود تکامل کا باعث بنتا ہے
اور دوسرا اہم موضوع پیغمبر اسلام کی مسؤلیت جو دوسروں کے مقابل میں ہے یعنی امر بالمعروف ( نماز ) قائم کرنے کا حکم ہے
۲۔ نماز کا اثر :
نماز کے بہت اہم آثار ہیں اسی لئے پیغمبر اسلام خود نماز پڑھتے اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تلقین کرتے تھے ۔
(اے نبی) آپ کی طرف کتا ب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
الف ۔ نماز گناہوں سے بچاتی ہے :
خداوند عالم اس آیت میں دو حکم دے رہے ہیں ۔
پہلا قرآنی آیات کی تلاوت اور دوسرا نماز کو قائم کرنا ۔ پھر اس کے بعد نماز کا فلسفہ بیان کرتاہے اور فرماتاہے کہ چونکہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے ۔
ب ۔ یاد خدا :
اسی آیت کے ضمن میں فلسفہ نماز شب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کا ذکر اس سے بھی بلند و بالا ہے ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اہم ترین آثار اور برکات میں سے ایک نہی عن المنکر سے بھی اہم ہے ۔وہ یہ کہ انسان کو خدا کی یاد دلاتاہے ہر خیر و سعادت کی جڑ شمار ہو تاہے۔
خداوند متعال نے اس مہم امر کو حضرت موسی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا
(أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِى
)اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔نماز کا اصلی ترین روح و فلسفہ یہی ذکر خدا ہے امام صادق اس
(ولذکر الله اکبر
)کی تفسیر میں فرماتے ہیں حلال و حرام کے وقت خدا کو یاد کرناہے ۔
پ ۔ گناہوں سے پاک ہونا :
ایک دن پیغمبر اسلام نے اپنے دوستوں سے پوچھا اگر تم میں سے کسی کے گھر میں صاف ستھرے پانی کی نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اپنے آپ کو اس پانی سے صاف کرتاہو تو کیا اس میں کوئی نجاست باقی رہے گی ؟ تو سب نے کہا نہیں یارسول اللہ تو فرمایا :
فَإِنَّ مَثَلَ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهَرِ الْجَارِي كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً كَفَّرَتْ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ
.
نماز اس جاری نہرکی طرح ہے جب بھی انسان نماز پڑھتاہے تو نمازوں کےدرمیان جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں ۔
ت۔ گناہ کو چھوڑنے کا اثر :
ایک جوان پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور گناہ بھی انجام دیتاتھا جب پیغمبر اسلام کو یہ بات بتائی گئی تو فرمایا :
انّصلاته تنهاه يوماً
۔ایک دن یہ نماز اس کو پلٹائے گی ۔
پیغمبر کے اصحاب نے بتایا کہ بہت زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اس نے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی ۔
ت ۔ غفلت اور تکبر کو ختم کرتا :
نماز کے سایہ میں انسان خدا کی یاد میں رہتا ہے اس وجہ سے غفلت سے نکل جاتے ہیں یاد خدا کے ساتھ انسان خدا کی جو عظمت دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی حقیر سمجھتا ہے اور تکبر سے بچ جاتا ہے ۔
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں
فَفَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ
خدانے ایمان کو لازم قرار دیاہے تاکہ شرک سے پاک ہوجائے اور نماز کو واجب قرار دیا ہے غرور کو ختم کرنے کے لئے ۔
سترواں جزء : امتحان الہی
(كلُُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَ الخَْيرِْ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُون
)۔
ہر نفس کو موت (کاذائقہ) چکھنا ہے اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں اور تم پلٹ کر ہماری طرف آؤ گے۔
۱۔ خیر اور شر کے ذریعے سے آزمایش ہونا :
بعض اوقات مشرکین کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کا کام دائمی نہیں ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو سارے کام ختم ہوجائیں گے جیسا کہ سورہ طہ کی آیت /۳۰ میں بیان ہوا ہے ۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ مرد اعتقاد رکھتا ہے کہ خود خاتم انبیاء ہے جو کبھی مرتانہیں تاکہ خود آئین کے محافظ ہو بس اس کی موت جب ہو جائے تو اس کا دعوی باطل ہو جائے گا ۔
قرآن مجید ابتداء میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی بشر کو آپ سے پہلے جاودانی زندکی عطا نہیں کی ہے مگر انہوں نے خود زندگی جاودان بنائی ہو ؟ پس مرنے کا قانوں سے کوئی استثناء نہیں ہے مرنے کا یہ قانون عمومی ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ناپائیدار یا باقی نہ رہنے والی اس زندگی کا مقصد اور ہدف کیا ہے ؟ قرآن مجید کہہ رہاہے کہ ہم آپ کو خیر اور شر سے آزمائش کریں گے اور سر انجام ہمارے پاس ہی لوٹ کر آو گے آپ کی اصلی جگہ وہی ہے اور یہاں پر آپ صرف امتحان کے لئے آئے ہو ۔
اس آیت میں لفظ شر خیر پر مقدم ہے چونکہ خدا کا امتحان جو بلاؤں پر ہوتا ہے وہ خیر کے امتحان و آزمائش سے بہت ہی سخت ہے
اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے جو آزمائش ہے وہ تربیت اور پرورش کے معنی میں ہے وگر نہ خدا وند عالم سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی طرح سے یہ امتحان ایک عمومی چیز ہے جس میں سب لوگ شامل ہیں ۔
کیا تم خیال کرتے ہو کہ یونہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ (وقت کا) رسول اور اس کے مومن ساتھی چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟(انہیں بشارت دے دی گئی کہ) دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔
۲۔ امتحان کے انواع و اہداف :
خداوند عالم مختلف انداز میں لوگوں کو امتحان میں ڈالتاہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ۔
اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات (کے نقصانات) سے ضرور آزمائیں گے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے ۔
اور اہداف الہی کے بارے میں ہم درجہ دیل نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔
الف ۔ نفوس کا پاک کرنا :
ایسا نہیں تھا کہ خدا وند متعال نے مومنین کو اس حالت پر کہ جس پر تم لوگ تھے اسی طرح چھوڑ دیاہو مگر یہ کہ ناپاک کو پاک سے جدا کیا ہے او ر ایسا بھی نہیں تھا کہ خدا نے آپ کو اپنے اسرار سے آگاہ کیا ہو تاکہ مومنین او رمنافقین کو اس راستے سے پہچانا جائے اور یہ سنت الہی کے خلاف ہے لیکن خداوند عالم رسولوں میں سے ایک کو رسول بناتے ہیں اور وہ رہبری کرنے کے لئے لازمی ہے ان کو بتا دیتے ہیں اور اسی کے اختیار میں قرار دیتے ہیں ۔
خدا اور رسول پر ایمان لائیں او ر پھر اس کے بعد تقوا اختیار کریں یہ تمہارے لئے ایک بہترین ہدیہ ہے ۔
ب ۔ مجاہدین اور صابرین کی شناخت :
اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں ۔
پ ۔ نیکو کاروں کی شناخت :
اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا، بخشنے والا ہے ۔
۳۔ امتحان الہی کے مقابل میں ہمارا وظیفہ :
الف ۔ صبر :
اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات (کے نقصانات) سے ضرور آزمائیںگے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے
ب ۔ امتحان الہی کو ہلکا سمجھنا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ۔
لَا تَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى تَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَة
مؤمن اس وقت تک مومن نہیں کہلاتا ہے جب تک وہ امتحان الہی کو نعمت نہ سمجھیں ۔
پ ۔ یاد خدا :
مؤمن کو جب بھی کوئی مصیبت آجاتی ہے تو کہتے ہیں: ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
ت۔ دعا :
امام علی علیہ السلام نے فرمایا
:قُلْ عِنْدَ كُلِ شِدَّةٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تُكْفَهَا
ہر سختی اور بلاء کے وقت لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو تو یہی کافی ہے ۔
اٹھارواں جزء : عفت و خویشنداری
(وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ نِكاَحًا حَتىَ يُغْنِيهَُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكاَتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا وَ ءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى ءَاتَئكُمْ وَ لَا تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلىَ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحََصُّنًا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الحَْيَوةِ الدُّنْيَا وَ مَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيم
)۔
جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہوں ان سے مکاتبت کر لو۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو اور تمہاری جوان لونڈیاں اگر پاکدامن رہنا چاہتی ہوں تو انہیں دنیاوی زندگی کے متاع کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقینا اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے ۔
۱۔ عفت کا حکم :
قرآن مجید کی ۳۲ ویں آیت میں ارشاد ہوتاہے کہ اور تم میں سے جولوگ مجرد ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکا ح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔
لیکن ہمیشہ شادی کے لئے وسیلہ فراہم نہ ہونے کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے کہ کئی عرصہ تک بغیر شادی کے گزارے اور اسی عرصے میں جنسی آلودگی کا شکار ہوتا ہے ۔ اسی وجہ سے اس آیت میں خدا وند عالم حکم دیتا ہے کہ پرہیز گار بنیں حتی کہ مشکل ہی کیوں نہ ہو
عفت اہم ترین اخلاقی فضایل میں سے جو شکم پرستی اور جنسی شہوت کے مقابل میں ہے عفت ایک ایسی صفت ہے کہ انسان کو شہوت ابھارنے سے روک دیتا ہے اور خواہشات نفسانی کو بچا کر رکھتا ہے عفت انسان کی ایک اندرونی چیز ہے جس طرح سے تقوا ظاہری ہے کہ انسان ظاہر ا گناہ سے بچنے کا نام ہے
حضرت یوسف کے قصے میں اور قرآن کی دوسری آیات میں اس اخلاقی موضوع پر تاکید ہوئی ہے اور سورہ مؤمنون میں خدا وند متعال نے عفت کو نماز اور زکات اور پرہیز گاری کو مؤمنین کے صفات میں ذکر کیا ہے ۔
پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ کسی نامحرم عورت یا کسی کنیز کے ساتھ نزدیکی کرے لیکن خدا کے خوف سے ایسا کام نہ کرے تو خدا اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتاہے اور ہر خوف سے اس کو حفظ و امان میں رکھے گا اور بہشت میں داخل کرے گا ۔
۲۔ عفت کے آثار :
الف ۔ شہوت کو کمزور کرنا :
الْعِفَّةُ تُضَعِّفُ الشَّهْوَةَ
.
۔عفت شہوت کو کمزور کرتی ہے ۔
ب۔ ایجاد قناعت :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں
:ثَمَرَةُ الْعِفَّةِ الْقَنَاعَةُ
.
۔عفت کا میوہ قناعت ہے ۔
پ ۔پاکیزہ اعمال:
بِالْعَفَافِ تَزْكُو الْأَعْمَالُ
.
۔عفاف کے ذریعے سے اعمال پاک ہو جاتے ہیں ۔
ح ۔ عزت :
الْعِفَّةَ وَ الْقَنَاعَةَ حَالَفَهُ الْعِز
.
جو بھی عفت اور قناعت کی پناہ میں آجائے اس کی عزت ظاہر ہوتی ہے ۔
ح ۔ بندگی کی انتہاء :
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں
۔مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ
.
۔خدا کے نزدیک پیٹ اور شرم گاہ کی
عفت سے بڑھ کر کوئی افضل چیز نہیں ہے ۔
اس آیت میں جنسی عفت کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے لیکن عفت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے جو محرمات اور واجبات کو بھی شامل ہے جیسا کہ پیٹ کی عفت شرمگاہ کی عفت اور مال کی عفت وغیرہ ۔
اور مولا علی علیہ السلام نے عفت کا بلند ترین درجہ خدا کی اطاعت اور تقوا کو فرض کیا ہے
۳۔ عفت کا ریشہ :
الف ۔ غیرت :
مولا علی علیہ السلام نے فرمایا :عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِه
مرد کی عفت اس کی غیرت کے مطابق ہوتی ہے ۔
ب ۔ قناعت :
اصل العفاف القناعه
۔عفت کا ریشہ قناعت ہے ۔
پ ۔ تعقل :
مَنْ عَقَلَ عَفَ
.
جو تعقل کرتاہے وہ عفیف ہوتاہے ۔
۴۔ بے عفتی کو روکنے کے راستے :
الف ۔حجاب اور خود آرائی کوترک کرنا :
حجاب کا حکم اسلام کے اہم ترین احکام میں سے ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات میں ذکر ہوا ہے جیسا کہ سورہ نور /۳۱ سورہ احزاب /۳۳۔ ۵۳ ۔۵۹ )
بے حجابی سے انسان کی شہوت تحریک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بے عفتی عام ہو جاتی ہے ۔
ب ۔ مرد اور عورت کا مخلوط نہ ہونا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے : مردوں اور عورتوں کو جدا رکھنا جب دونوں کی نظریں مل جائیں تو اس سے ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ۔
پ ۔ اپنی آواز کو باریک نہ بنائیں ۔
قرآن مجید نے یہاں تک پیغمبر کی بیویوں کو بھی توصیہ کیا ہے کہ گھر سے باہر نہ جایا کریں اے نبی کی بیویو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا دو ۔۔۔۔
(ا فَلَا تخَضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فىِ قَلْبِه
)۔
ث ۔ اشرار کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے :اشرار کے ساتھ ہم نشینی شر کا سبب بنتاہے جس طرح سے کہ کسی مردہ پر ہوا لگ جاتی ہے تو وہ ہوا بدبو ساتھ لیکر آتی ہے اور ہر جگہ پھیلا دیتی ہے
ت ۔ مد مقابل کی عفت :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ۔عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ
.
دوسروں کی عورتوں کی عفت کا خیال رکھو تاکہ دوسرےبھی تمہاری عورتوں کی عفت کا خیال رکھیں ۔
ج ۔ اپنی رفتار اور آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا :
آپ مومن مردوں سے کہدیجئے: وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث
ہے
۔
چ ۔ اعتقاد اور قبول :
پیغمبر اسلام نے فرمایا :طُوبَى لِمَنْ تَرَكَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعُودٍ لَمْ يَرَهُ
.
۔خوش قسمت ہے وہ انسان جو شہوت کو بہشت کے وعدے پر جوکہ دیکھا نہیں ترک کرتاہے ۔
خ ۔ حیا کی وسعت :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔مَنْ لَوْ لَا الْحَيَاء..... وَ لَمْ يَعِفَّ عَنْ فَاحِشَة
.
۔لوگوں کو اگر حیا نہ ہو تو کوئی بھی فاحشہ برے کام سے نہیں روکا جاتا ۔
د ۔ شادی :
پیغمبر اسلام نے فرمایا : ہر جوان اگر اپنی ابتدائی زندگی میں شادی کرے تو شیطان واویلا کرتاہے کہ اس نے اپنے دین کو مجھ سے حفظ کیا ہے
ذ ۔ فارغ وقت کو پر کرنا :
امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
مِنَ الْفَرَاغِ تَكُونُ الصَّبْوَةُ
..
فراغت کے اوقات جوانی کے نادان اوقات میں سے ہیں لہذا فراغت اور فضول اوقات کو پر کرنا چاہیے ۔
انیسواں جزء : دوستی کرنا :
(وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلىَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنىِ اتخَّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَاوَيْلَتىَ لَيْتَنىِ لَمْ أَتخَّذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَّقَدْ أَضَلَّنىِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنىِ وَ كَانَ الشَّيْطَنُ لِلْانسَنِ خَذُولا
).
اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا: کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔
ہائے تباہی! کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جب کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغا باز ہے۔
۱۔ کاش کہ دوستی نہ کرتا :
پیغمبر اسلام کے زمانے میں دو مشرک ( عقبہ اور ابی )دونو ں دوست تھے اور جب بھی عقبہ سفر سے واپس آتے تھے کھانے کا انتظام کرتے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور اسی وقت چاہتے تھے کہ پیغمبر کے پاس بھی جائے اگر چہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ایک دن پیغمبر اسلام کو بھی دعوت کی تھی جب دستر خوان بچھایا گیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب تک آپ خداکی وحدانیت اور میری پیغمبری کا اعلان نہیں کریں گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤنگا تو اس نے اقرار کیا تو پیغمبر نے کھانا شروع کیا ۔ جب یہ بات اس کے دوست ابی تک پہنچ گئی تو وہ عقبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم اپنے آئین سے منحرف ہو گئے ہو کیا؟ عقبہ نے کہا نہیں لیکن مجھے شرم آئی کہ پیغمبر کھانا کھائے بغیر چلے جائیں اسی وجہ سے شہادتیں زبان پر جاری کیا تو ابی نے کہا میں کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہونگا یہاں تک کہ تم پیغمبر کے سامنے جاکر اس کی بے عزتی کرو ۔ اور عقبہ نے ایسا ہی کیا اور وہ مرتد ہوگیا اور جنگ بدر میں مارا گیا اور اس کا دوست جنگ احد میں واصل جہنم ہوگیا
اوراوپر والی آیات نازل ہوئیں اور غلط دوست کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا ۔
انسان کا دوست اور ہم نشین اس کی زندگی میں بہت ہی اثر رکھتا ہے جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا :
فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دِينَهُ فَانْظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ فَإِنْ كَانُوا أَهْلَ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَى دِينِ اللَّه
جب بھی تمہیں کسی پر شک ہو اور اس کی دینداری کےبارےمیں معلوم نہ ہو تو اس کے دوستوں کی طرف نگاہ کرنا اگر وہ دیندار ہیں تو وہ بھی اسی دین کی پیروی کرنے والا ہوگا اور اگر دین خدا پر نہ ہو تو وہ بھی اس دین سے دور ہوگا ۔
برے دوست کے انسان پر اثرات کے بارے میں امام جواد علیہ السلام فرماتے :مُصَاحَبَةَ الشَّرِيرِ، فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، يَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَ يَقْبُحُ أَثَرُهُ
.
برے دوستوں سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی مانند ظاہر میں بہت ہی اچھے اور باطن میں اس کا اثر بہت ہی خراب ہے ۔
۲۔ برے دوستوں سے ہم نشینی کا اثر :
الف ۔آخرت کی نابودی :
برے دوستوں کے ساتھ رہنے کا اہم تیرین اثر جو کہ آیت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے برےدوست انسان کی آخرت کو برباد کرتا ہے ۔ اسی لئے مولا علی فرماتے ہیں کہإِيَّاكَ وَ مُعَاشَرَةَ الْأَشْرَارِ فَإِنَّهُمْ كَالنَّارِ مُبَاشَرَتُهُمْ تُحْرِقُ
.
.شریر لوگوں کی ہم نشینی سے پرہیز کرو چونکہ وہ آگ کی طرح ہیں وہ ردوسروں کو بھی جلا دیتے ہیں ۔
ب ۔ فساد اخلاقی :
امیر المؤمنین کا فرمان ہے :فَسَادُ الْأَخْلَاقِ مُعَاشَرَةُ السُّفَهَاءِ
.
۔بے وقوف کے ساتھ رہنے سے انسان کا اخلاق فاسد ہو جاتا ہے ۔
پ۔ تنہائی واقعی :
امیر المؤمنین کا فرمان ہےأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ قَرِينُ السَّوْءِ
.
۔سب سے بڑی تنہائی برے دوست کے ساتھ بیٹھنا ہے ۔
ث ۔تا ثیر پذیری :
امیر المؤمنین کا فرمان ہےصُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تَكْسِبُ الشَّرَّ كَالرِّيحِ إِذَا مَرَّتْ بِالنَّتْنِ حَمَلَتْ نَتْناً
.
برے دوست کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے ہوا کی طرح کہ جب کسی مردے پر پڑتی ہے تو بدبو کو ساتھ لیکر آتی ہے ۔
۳۔ اچھے دوست :
الف ۔ غصہ پر کنٹرول کرنا :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے : جو بھی تمہارے اوپر تین بار غصہ کرے اور آپ کی اچھائی اور برائی کے بارےمیں کچھ نہ کہے تو اس کو اپنا دوست انتخاب کرو
ب ۔ سبب افتخار و زینت کا:
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے : ایسے بندے کے ساتھ رہنا جو آپ کے لئے زینت بن جائے نہ کہ آپ اس کے لئے زینت بنو
ت ۔ صاحبان عقل :
امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے: عقلمند کے ساتھ دوستی کرو اور عالم کے ساتھ رہا کرو اور اپنے نفس پر کنٹرول کرو تاکہ تم بلند درجہ پر پہنچ سکو
ث۔ آخرت کی طرف دعوت دینے والے :
امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے:مَنْ دَعَاكَ إِلَى الدَّارِ الْبَاقِيَةِ وَ أَعَانَكَ عَلَى الْعَمَلِ لَهَا فَهُوَ الصَّدِيقُ الشَّفِيقُ.
جو شخص تمہیں قیامت کی طرف دعوت دےاور اچھی عمل میں تمہاری مدد کرے تو وہ تمہارا بہترین دوست ہے ۔
ت ۔ دین اور دنیا میں فائدہ پہنچانے والا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ۔مَنْ لَمْ تَنْتَفِعْ بِدِينِهِ وَ دُنْيَاهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي مُجَالَسَتِه
.
جو شخص دین اور دنیا کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہو اس کے ساتھ بیٹھنا خیر نہیں ہے ۔
خ ۔ شرائط جامع :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے : دوستی کرنے کی کوئی حد ہوتی ہے اور اگر کوئی ان میں سے بعض کو بھی رکھتا ہو تو اس کے ساتھ دوستی کرو اور اگر ایسا نہ ہو تو خود کو اس کے ساتھ دوستی کی نسبت نہ دو ۔
پہلا ۔ اس کا ظاہر اور باطن دونوں آپ کے لئے اچھا ہو ۔
دوسرا ۔ آپ کی عزت کو اپنی عزت اور آپ کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہو ۔
تیسرا ۔ ولایت اور مال کو تمہارے مخالفت میں استعمال نہ کرے۔
چوتھا ۔ اور جتنے ہو سکے تمہیں منع نہ کرے۔
پانچواں
جو تمام خصوصیتوں کا جامع ہے نکبت کے وقت آپ کو تسلیم نہ کرے۔
چ ۔ گناہ سے منع کرنا :
امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے:الصَّدِيقُ مَنْ كَانَ نَاهِياً عَنِ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ مُعِيناً عَلَى الْبِرِّ وَ الْإِحْسَانِ
.
دوست وہ ہے جو ظلم اور دشمنی سے تمہیں روک دے اور نیکی و احسان میں تمہارے مددگار بنیں ۔
۴۔ وہ عوامل جو دوستی میں کمی اور اضافہ کا سبب بنتے ہیں :
الف ۔ سوء ظن :
امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے: سوء ظن آپ پر غالب نہ آئے چونکہ آپ اور آپ کے دوست کے درمیان عفو و درگزر ختم ہو جاتی ہے
ب ۔ دوستی میں کمی ہونے کے تین عوامل :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے :امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو وصیت کی ۔ عجب اور سوء ظن و بد خلقی اور کم صبری سے
پرہیز کرو چونکہ ان تینوں کے ساتھ ہونے سے تمہارے لئے کوئی ہم نشین نہیں رہے گا۔
پ ۔ اشکال :
امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے:مَنْ نَاقَشَ الْإِخْوَانَ قَلَّ صَدِيقُهُ
.
جو کوئی اپنے بھائی پر اشکال کرے تو اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں ۔
ث ۔ دوست زیادہ ہونے کے تین عامل :
امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا : جس کے اندر حلم اور کرم اور ورع ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے نیک بھائی کی تعریف کرنے سے دشمنوں پر غلبہ پاتے ہیں
بیسواں جزء حیاء :
(فجََاءَتْهُ إِحْدَئهُمَا تَمْشىِ عَلىَ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبىِ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تخَفْ نجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ
)
پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی: میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دیں، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے: خوف نہ کرو، تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔
۱۔ داستان حیا :
حضرت موسی علیہ السلام جب فرعونیوں کے ہاتھ سے بھاگ کر مدین پہنچ گئے تو وہاں پر ایک گروہ کو دیکھا جو اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے اور انہی میں سے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں حضرت موسی نے نزدیک جاکر ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ سارے لوگ اپنے مال مویشی کو پلائیں تب تک ہم انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے والد محترم بہت ہی بوڑھے ہیں تو حضرت موسی نے ان کی مدد کی اور ایک کونے میں جاکر آرام کرنے لگے کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ دونوں دوبارہ آگئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا والد آپ کو بلارہا ہے تاکہ ہماری مدد کرنے کی اجرت آپ کو دے دیں ۔
۲۔ حیا کے آثار :
حیا کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور رہتا ہے قرآن مجید کی آیات اور روایات میں حیا کے لئے اہم ترین آثار کو ذکر کیا ہے ۔
الف ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :
بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر حیا نہ ہوتا تو وہ اپنے والدین کے حق کو ادا نہیں کرتے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے اور امانت میں خیانت کرتے اور ہر طرح کی برائیوں میں مشغول ہوتے
ب ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے ۔
کوئی بندہ اگر خدا وند متعال سے حقیقی طور پر حیا کرے تو ۔ ۱ ۔ موت کو اپنے آنکھوں سے یقینی طور پر دیکھتا ہے ۔۲ ۔دنیا اور اس کی زینت سے بے رغبتی ہو جاتی ہے ۔۳۔اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے ۔ ۴ ۔ اپنے پیٹ اور دوسری چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے ۔ ۵۔ اور قبر وغیرہ کو نہیں بھولتا
ج ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے :
حیا سے نکلنے والی چیزیں : ۱۔ نرمی ۲ مہربانی ۳۔ خدا کا خوف ۴۔ سلامتی ۵۔ شر سے دوری ۶۔ خوشحالی ۷۔ بزرگواری ۸۔ کامیابی ۹۔ اس کی تعریف ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ با حیا انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں ۔
۳۔ حیا کے انواع :
سورہ قصص کی آیت /۲۵ میں حضرت شعیب کی بیٹیوں کے حیا کے بارے میں بتایا گیا ہے ۔ حیا انسانوں کے ساتھ خصوصا جنس مخالف کے ساتھ رابطہ نہ رکھنا ہے قرآن مجید اس طرح کے روابط اور خصوصا نامحرم سے رابطہ نہ کرنے والے اور معیار کو بیان کرتا ہے ۔
انواع حیا درجہ ذیل ہیں ۔
الف ۔ خود سے حیا کرنا :
امام علی علیہ السلام نے فرمایا :أَحْسَنُ الْحَيَاءِ اسْتِحْيَاؤُكَ مِنْ نَفْسِكَ
.
انسان کے لئے بہترین حیا اپنے سے حیا کرنا ہے ۔
ب۔ خدا اور لوگوں سے حیا کرنا :
پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے :اسْتَحْيِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْتِحْيَاءَكَ مِنْ صَالِحِي جِيرَانِكَ
خداوند عالم سے شرم و حیا رکھو اور اسی طرح سے اپنے نیک اور صالح ہمسایہ سے حیا رکھو ۔
پ ۔ خدا سے حیا کرنا :
امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا :خف الله لقدرته عليك و استح منه لقربه منك.
.خدا سے اس کی قدرت کی وجہ سے ڈرو اور اس سے حیا کرو چونکہ وہ تمہارے بہت ہی نزدیک ہے ۔
ت۔ پیغمبر اسلام اور فرشتوں سے حیا کرنا :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے :فَلْيَسْتَحْيِ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى نَبِيِّهِ الْعَمَلُ الْقَبِيحُ
ہوشیار ہوجاو تم میں سے ہر ایک پیغمبرکے حضور میں برا کام انجام دینے سے شرم و حیا کرو ۔
پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے :ليستحي أحدكم من ملكيه اللّذين معه
تم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھ والے دو فرشتوں سے حیا کرو ۔
۴۔ حیا کا منشا:
حیا کا اہم ترین سرچشمہ درجہ ذیل ہیں ۔
الف ۔ ایمان اور یقین :
امام علی علیہ السلام نے فرمایا :كَثْرَةُ حَيَاءِ الرَّجُلِ دَلِيلُ إِيمَانِهِ
.
بندے کا زیادہ حیا اس کے ایمان کی علامت ہے ۔
ب ۔ خدا کے نزدیک ہونے کا احساس کرنا :
أَ لَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ۔
یہ آیت خدا کے نزدیک ہونے اور حاکم ہونے کی نشاندہی کرتی ہے ۔ اسی لئے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیںاسْتَحْيِ مِنْهُ لِقُرْبِهِ مِنْكَ
..
خداکے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس سے شرم و حیا کرو ۔
۵ ۔ بے حیائی کے آثار :
بے حیا انسان نہ ہی خدا سے اور نہ ہی فرشتوں سے اور نہ ہی دوسرے لوگوں سے حیاکرتا ہے بلکہ وہ ہر دیوار کو توڑتا ہے اور ہر گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے اسی لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا :مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ لَا غِيبَةَ لَهُ
.
.جو بھی حیا کے پردے کو اٹھالے تو پھر غیبت کرنے کو کوئی چیز اس کے مانع نہیں بنتی ۔
اورپھر فرمایا :ان آخر ما یتعلق به اهل الجاهلیه من کلام النبوة : اذا لم تستح فاضع ما شئت
.
کلام نبوت اہل جاہل کے لئے یہ تھی کہ اگر حیا نہیں ہے تو جو انجام دینا چاہتے ہو انجام دو ۔
اکیسواں جزء : امر بالمعروف و نہی عن المنکر
(يَابُنىََّ أَقِمِ الصَّلَوةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبرِ عَلىَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور
)۔
اے بیٹا! نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پر صبرکرو، یہ امور یقینا ہمت طلب ہے ۔
۱۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے پر صبر کرنا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھا لیکن وہ ایک مخلص اور ایماندار اور زیادہ فکر کرنے والا انسان تھا خدا پر مکمل یقین رکھتا تھا اور اس کے ساتھ دوستی تھی اور خدابھی اس کو دوست رکھتا تھا جس کی وجہ سے خدا نے انکو حکمت عطا کی
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اورنماز پہلے والی امت پر بھی واجب تھا اور والدین پر یہ فرض بنتا ہےکہ اپنے بچوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں ۔
اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو یہ مسؤلیت بھی سونپ دے اسی طرح سے فقط حق کے راستے پر ہی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس حق کی طرف دعوت دی جائے ۔
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں موجود رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے ۔
قرآن مجید صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ صالح بندوں کا راستہ ہے اس آیت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں ۔ اور اسی طرح سے سورہ مریم میں بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز اور روزے کا حکم دیتے تھے
اور سورہ اعراف میں اس امر کو پیغمبر اکرم کی خصوصیات میں بیان کیا گیا ہے
(يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنهْئهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ
).
اور اسی سے مربوط آیات سورہ آل عمران /۱۱۔ ۱۰۴ ۔ ۱۱۴ اور لقمان /۱۷ توبہ / ۶۷ ۔ ۷۱ ۔۱۱۲ ہود /۸۸ )
قرآن مجید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مومنین کی خصوصیات میں سے جانتاہے اور فرماتا ہے(
التَّئبُونَ الْعَبِدُونَ الحْمِدُون
)
اور اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ :وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر
.
انسان کے تمام اعمال یہاں تک کہ خداکی راہ میں جہاد کرنا بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نسبت سے ایسا ہے دریا کے پانی کی نسبت لعاب دہن کے برابر ہے ۔
۲۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آثار :
الف ۔ واجبات کو انجام دینا :
امام علی علیہ السلام نے فرمایا : جب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے تو تمام واجبات الہی آسانی سے انجام پاتے ہیں کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کے حقوق کو حقدار تک پہنچا دیتا ہے اور غنائم کو صحیح طریقے سے تقسیم ہوجاتا ہے اور صدقہ کو مستحق تک پہنچادیتا ہے
ب ۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر تین صفات پائی جاتی ہیں تو اس کی دنیا و آخرت دونو ں سالم رہتے ہیں ۔
۱۔ کوئی امر بالمعروف کرتا ہو اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہو ۔
۲۔ کوئی امر بالمعروف کرتا ہو اور اس کو قبول کرتا ہو ۔
۳ ۔ اور قانو ن اور حدود الہی کے پابند ہو
۳۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑ نے کے اثرات :
الف ۔ اشرار کی حکومت :
پیغمبر اسلام نے فرمایا : جب لوگ نہی عن المنکر کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو تلقین کررہے ہیں اور اس کا نتیجہ خیر و سعادت ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو خیر و برکت کو ان سے اٹھایا جاتاہے اور ان پر شریر لوگوں کو مسلط ہو جائے گا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو گا
ب ۔ بلاؤ ں کا نازل ہو نا :
امام زین العابدین نے فرمایا : وہ گناہیں جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں ۔ بے گناہ لوگوں کی مدد نہ کرنا اور مظلوموں کی حمایت نہ کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا ہے ۔
پ ۔ ارزش کا ختم ہو جانا :
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے سے انسان گناہ کا ر آسانی سے گناہ کرسکتا ہے اور واجبات آسانی سے ترک ہو جاتے ہیں
پیغمبر اکرم نے فرمایا جب تمہاری عورتیں فاسق ہو جائیں گی تو تمہاری کیا حالت ہو گی جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کریں ۔ کہا گیا یارسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا ؟ تو فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا برے کاموں کی تلقین ہو گی اور اچھے کام سے منع ہو گا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو گا ؟ تو کہنے لگے اس سے بھی بد تر ہو گا لوگ اچھے کاموں سے دور ہونگے اور اس کو ناپسند کریں گے اور برے کاموں کی تلقین کرنے کو پسند کریں گے یعنی معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھا جائےگا ۔
۴۔ بے تقاوتی کیوں ؟
بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لئے مانع بن جائیں گے ۔
گناہ اور غیرگناہ کے درمیان فرق نہ ہونا اور شرم و خوف اور لوگوں کی راحت طلبی اور فکر ی انحرافات اور بے جا توقعات
اوربے مسؤلیتی اور ناامیدی جیسے عوامل ہیں لیکن ہم انہی میں سے صرف دو عامل کو ذکر کریں گے ۔
الف ۔ ضرر سے خوف کرنا :
امیر المؤمنین نے فرمایا : اے لوگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے مو ت قریب نہیں آتی اور رزق میں کمی نہیں آتی ہے ۔
ب ۔ بے شرمی :
امیر المؤمنین نے فرمایا :مَنِ اسْتَحْيَى مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ فَهُوَ أَحْمَقُ
.
اگر کوئی حق بات کرنے سے شرماتا ہے تو وہ بے وقوف ہے ۔
بائیسواں جزء : غیرت
(لَّئنِ لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَفِقُونَ وَ الَّذِينَ فىِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فىِ الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَ قُتِّلُواْ تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فىِ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَ لَن تجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا
)
اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے پھر وہ اس شہر میں آپ کے جوار میں تھوڑے دن ہی رہ پائیںگے۔ یہ لعنت کے سزاوار ہوں گے، وہ جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیںگے۔ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔
۱۔ دین اور ناموس سے دفاع کرنے کا آلہ :
مدینہ میں تین گروہ ایسے تھے جو خراب کاری کرتے تھے ۔ ۱ ۔ منافقین ۲۔ اوباش و ہوس پرستان ۳۔ اور اسلام کے خلاف افواہیں پھیلانے والے ۔ قرآن کریم نے ان تین گروہ کی شدید مذمت کی ہے
اور یہ غیرت پر دلالت کرنے کی اہم ترین آیات ہیں ۔ غیرت کا معنی شدت کے ساتھ اپنے مال اور ناموس کی حفاظت کرناہے اور ان کے علاوہ تمام ارزش بغیر دفاع کے رہ جاتی ہیں اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معاشرہ اور حکومت نہ صرف اوباش اور منافقین اور دل کے مریضوں کے مقابل میں بے تفاوت نہیں ہونی چاہیے اور ان سے سخت ترین برخورد ہونی چاہیے اور سورہ احزاب آیت /۳۲ اس کی تصویر کشی کرتی ہے اور اس آیت کے آخر میں اشارہ ہوتا ہے کہ یہ صرف حکم اسلام کے ساتھ منحصر نہیں ہے اور قابل تغیر بھی نہیں ہے ۔
۲۔ غیرت کے آثار :
الف ۔ اپنے خاندان کی حفاظت :
اگر انسان کے پاس غیرت ہو تو اس کا گھر ایک امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے اسی لئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
انسان اپنے گھر اور خانوادہ میں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کی طبیعت میں نہ بھی ہو تب بھی زحمت کر کے حاصل کرنی چاہیے ۔ بہترین معاشرہ اور ایک اندازہ کے مطابق توسعہ اور برائیوں سے حفظ و نگہداری کے ساتھ غیرت
ب ۔ شخصیت ۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ
.
جب انسان کے پاس غیرت نہ ہوتو اس کا دل برعکس ہو جاتا ہے ۔
پ ۔ عفت :
امیر المؤمنین کا فرمان ہےقَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِه
.
انسان کی ارزش اس کی ہمت کے مطابق ہے اور اس کی شجاعت اس کی عزت نفس کے مطابق ہے اور اس کی عفت اس کی غیرت کے مطابق ہے ۔
ث ۔ گناہ کو ترک کرنا :
غیرت کے اہم ترین آثار میں سے ایک گناہ کو چھوڑنا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا
:مازنی غیور قط
غیرت مند انسان کبھی بھی زنا نہیں کرتا ہے ۔
اسی بنا پر گناہ سے بچنے کے عوامل میں سے ایک عفت اور غیر ت کو معاشرہ میں پیداکرنا ہے ۔
۳۔ غیرت کا منشا :
غیرت کا اہم ترین سرچشمہ ایمان ہے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ۔إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ
.
انسان کی غیرت اس کے ایمان سے ہے
ایمان انسان کو اپنی ناموس سے دفاع کرنے کی تلقین کرتا ہے اور جو اپنی ناموس کی دفاع میں کوئی حرکت نہیں کرتا ہے تو اس کی ایمان میں مشکل ہے اسی لئے پیغمبر اسلام کی حدیث میں تاکید ہوئی ہے کہ ۔ خداوند متعال کے لئے غیرت ہے اور انسان کےلئے بھی ایک غیرت ہے اور خدا کی غیرت یہ ہے کہ جب مومن پر خدا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے لیکن وہ اس کو انجام دیتا ہے
اسی وجہ سے ایماندار انسان غیرت مند شمار ہوتا ہے
تیئسواں جزء :اخلاص اور صدق نیت
(قُلْ إِنىِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مخُلِصًا لَّهُ الدِّين
).
کہدیجئے: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں ۔
۱۔ گوہر اخلاص :
خداوندمتعال پیغمبر اسلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کہو کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کی خالصانہ عبادت کروں اور اخلاص دین اسلام میں ہر با ارزش عمل کے لئے ایک عامل شمار ہوتا ہے ۔
(فَادْعُواْ اللَّهَ مخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
)
۔ پس دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کوپکارو اگرچہ کفار کو برا لگے ۔
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانو ں کے دلوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے ۔عمل کو صرف خدا کے لئے خالصانہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں اور اماموں کے لئے خیرخواہی اور انکی جماعت کے ساتھ خیر خواہی
حدیث قدسی میں پیغمبر اسلام سے نقل ہوا ہے کہ فرمایا اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور ہر اس شخص کے دل میں امانت کے طور پر رکھتا ہوں جس کو میں دوست رکھتا ہوں ۔
اخلاص نیت سے مراد یہ ہے کہ ہر کام میں فقط خدا کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہیں دینا چاہیے ۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے عبادت کرنے والا خدا کی عبادت کا حق اس وقت تک ادا نہیں کرسکتا ہے جب تک وہ تمام مخلوق خدا کو چھوڑ کر صرف خدا کی ذات کی طرف متوجہ نہ ہو ۔اسی وقت میں خدا وندمتعال فرماتے ہیں یہ بندہ میرے لئے خالص ہوا ہے اور اپنے کرم کی وجہ سے اس کو قبول کرتا ہے
۔
اسی بلند ترین ارزش کی وجہ سے اخلاص کو اختیار کرنا بہت ہی سخت اور دشوار ہے لذا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ :
تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَل
.
خالصانہ عمل کرنا کام کرنے سے زیادہ سخت ہے ۔
اخلاص عمل کے لئے بہترین نمونہ وہی امام علی علیہ السلام کی رفتار ہے کہ جب عمر بن عبدود نے آپ کی طرف لعاب دہن کا اشارہ کیا ۔
۲۔ اخلاص کے آثار :
اگر کوئی اپنی زندگی میں اخلاص کو اپنائے تو اس کی زبان سے حکمت کے جملے جاری ہوتے ہیں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ
مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلَّا جَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ
.
جو شخص چالیس دن تک مخلصانہ عبادت کرے تو اس کے دل اور زبان سے حکمت جاری ہوتی ہے ۔
اور اسی اخلاص کا نتیجہ غیر خدا کی طرف نیت کرنے سے پاک و منزہ ہوتا ہے ۔لَوْ خَلَصَتِ النِّيَّاتُ لَزَكَتِ الْأَعْمَالُ
.
اگر نیت خالص ہو جائے تو تمام اعمال پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں ۔
عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِخْلَاصِ تَسْتَنِيرُ الْبَصَائِرُ
.
اخلاص جب تحقق پیدا کرتا ہے تو انسان کی چشم بصیرت نورانی ہو جاتی ہے ۔
فِي إِخْلَاصِ النِّيَّاتِ نَجَاحُ الْأُمُورِ
.
۔تمام امور میں کامیابی اخلاص نیت ہے ۔
۳۔ موانع اخلاص :
الف ۔ھوای نفس ۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا :كَيْفَ يَسْتَطِيعُ الْهُدَى مَنْ يَغْلِبُهُ الْهَوَى
؟
کیسے ہدایت کی قدرت رکھتا ہے جس پر ہوای نفس غالب ہو ۔
پ ۔ لمبی آرزو :
قَلِّلِ الْآمَالَ تَخْلُصْ لَكَ الْأَعْمَالُ
.
اپنی آرزو کو کم کرو تاکہ آپ کے اعمال آپ کو خالص بنائیں ۔
پ ۔ ریا :
ریا اصل میں انسان کے اعمال کو بے ارزش اور فضیتلوں کو خراب اور تمام اعمال الہی کو فاسد کردیتا ہے ۔
اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، پس اس کے خر چ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سے مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینہ برسے اور اسے صاف کر ڈالے، (اس طرح) یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ کافروں کی راہنمائی نہیں کرتا
چوبیسواں جزء : عبرت
(وَ إِنَّ لَكمُْ فىِ الْأَنْعَامِ لَعِبرْةً نُّسْقِيكمُ مِّمَّا فىِ بُطُونهِا وَ لَكمُْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنهْا تَأْكلُونَ وَ عَلَيهْا وَ عَلىَ الْفُلْكِ تحُمَلُون
).
اور تمہارے لیے جانوروں میں یقینا ایک درس عبرت ہے، ان کے شکم سے ہم تمہیں (دودھ)پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے (دیگر) بہت سے فوائد ہیں اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوارکیے جاتے ہو۔
۱۔ عبرت لینا :
خداوندمتعال یہاں پر مبدااور معاد اور طغیان کے عواقب کے بارے بیان کرنے کے بعد گزشتہ لوگوں کے بارے میں عبر ت لینے اور ان کا مطالعہ کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے ۔ اور خصوصا فرعونیوں کی داستان سے عبرت حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس آیت میں لوگوں سے کہہ رہا ہےکہ زمیں میں سیر کریں اور سرکش لوگوں کا انجام اور ان کی جلی ہوئی ہڑیوں سے عبرت لے لیں اور جو لوگ بہت ہی مالدار تھے ان کی عاقبت کی طرف نظر دوڑائیں ۔
اور دوسرے مرحلہ میں گزشتہ لوگوں کی سرنوشت کے بارے میں ذکر کرتا ہے تاکہ آئندہ آنے والے ان سے عبر ت حاصل کریں اور ان سے دوری کرنا ان کی اس سرنوشت میں گرفتار نہ ہو جائیں اسی لئے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو گرفت میں لے لیا اور ان کو عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں تھا ۔اس کے بعد وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہوں نے خدا کی طرف سے بھیجے گئے نمائندوں کا انکار کرتے تھے ۔
امام صادق علیہ السلام اباذر کے بارے میں فرماتے ہیں خدا وند اباذر پر رحمت کرے کہ ان کی ساری عبادات تفکر اور عبر کے ساتھ تھی
۲۔ عبرت کے عوامل اور سرچشمہ :
الف ۔ فکر اور تامل :
امیر المؤمنین کا فرمان ہےمَنْ تَأَمَّلَ اعْتَبَر و مَنِ اعْتَبَرَ حَذَرَ
جو بھی تامل او رفکر کرے گا تو وہ عبرت حاصل لے گا اور جو عبرت حاصل کرے گا وہ گناہوں سے دور رہے گا ۔
ب ۔ بصیرت ۔
امیر المؤمنین کا فرمان ہےبِالاسْتِبْصَارِ يَحْصُلُ الِاعْتِبَارُ
.
بصیرت عبرت لینے سے حاصل ہوتی ہے ۔
پ ۔ تعقل اور اندیشہ :
امیر المؤمنین کا فرمان ہے :كَسْبُ الْعَقْلِ الِاعْتِبَارُ وَ الِاسْتِظْهَارُ وَ كَسْبُ الْجَهْلِ الْغَفْلَةُ وَ الِاغْتِرَارُ
.
عقل کا نتیجہ عبر ت لینا اور کامیاب ہونا ہے اور جہل کا نتیجہ عفلت اور ضرر لینا ہے ۔
ت ۔ خشیت :
عبر ت حاصل کرنے کے لئے خشیت اور تواضع ایک اہم عامل شمار ہوتا ہے ۔ اسی بنا پر خدا وند متعال فرماتے ہیں ۔
(إِنَّ فىِ ذَالِكَ لَعِبرْةً لِّمَن يخَشى
).
۳۔ عبر ت کے آثار :
الف ۔ گناہوں کی طرف متوجہ ہونا :
سورہ مومن کی اکیسویں آیت میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین پر سیر کرنے کا مقصد گنہکاروں کی عاقبت کو دیکھنا ہے ۔
ب ۔ گناہوں سے پاکیت :
عبرت حاصل کرنے کا اہم ترین عامل کہ جب انسان اپنے تلخ حوادث کو دیکھتا ہے تو گناہوں سے ہاتھ اٹھاتاہے ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا :الاعتبار بثمرة العصمه
عبرت لینے کے نتیجے میں عصمت حاصل ہوتی ہے ۔
پ ۔ طمع کم کرنا :
امام علی علیہ السلام نے فرمایا :مَنِ اعْتَبَرَ بِغِيَرِ الدُّنْيَا قَلَّتْ مِنْهُ الْأَطْمَاع
جو بھی اس بدلتی دنیا سے عبرت لے گا تو اس میں طمع کم ہو گا۔
پچیسواں جزء : گناہان کبیرہ سے دور رہنا
(وَ الَّذِينَ يجَتَنِبُونَ كَبَئرِ الْاثمِْ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُون
)۔
اورجوبڑے بڑے گناہوںاوربے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔
۱۔ گناہ کبیرہ سے دور رہنا :
گزشتہ آیات میں وہ مومنین جو خدا پر توکل کرتے ہیں ان کے اجر اور پاداش کے بارے میں تھا اور یہاں پر توکل اور ایمان کی صفت کے بعد ان کے سات قسم کے برناموں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے جو ایک سالم جامعہ اور معاشرے کے لئے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اور اولین صفت پاکسازی سے شروع کرتے ہوئے فرمارہا ہے کہ پاداش الہی اور جو اس کے پاس ہے وہ ان بندوں کے لئے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں ۔
کبائر : کبیرہ کی جمع ہے جس کا معنی بڑے گناہ کے ہیں بعض نے ان کو ایسے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں عذاب کرنے کا وعدہ دیا ہے اور بعض نے ایسے گناہ مراد لیا ہے جن میں حد شرعی جاری ہوتی ہے ۔
کہا گیا ہے کہ لغت میں جو کبیرہ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے مراد ہر وہ گناہ ہے جو اسلام کی نظر میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لئے عذاب الہی کا وعدہ دیا ہے جیسا کہ ہم روایت میں پڑھتے ہیں
۔الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ
.
ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا نے جہنم کی آگ ان پر واجب کیا ہے ۔
۲۔ گناہان کبیرہ قرآن میں :
الف ۔ شرک خدا ۔ ب۔ رحمت خدا سے ناامید ہونا ۔ ت ۔ مکر خدا سے امان میں رہنا ۔ ث ۔ عاق والدین ۔ج ۔ قتل مؤمن ۔ چ ۔ پاک دامن عورتوں کے ساتھ نارواں سلوک کرنا ۔ ح ۔ یتیم کا مال کھانا ۔خ ۔ جنگ سے بھاگ جانا ۔ د ۔ ربا کھانا ۔ ر ۔ جادو
ز ۔ زنا کرنا ۔ س ۔ جھوٹی قسم کھانا ۔ ش ۔ خیانت کرنا ۔ ص ۔ زکاۃ واجب کو ادا نہ کرنا ۔ ض ۔ حق بات کو چھپا کر جھوٹی گواہی دینا ۔ ط ۔ شراب پینا ۔ ظ ۔ بے وفائی کرنا : ع ۔ قطع رحم کرنا
۳۔ چھوٹے گناہوں کے بخشنے کا فلسفہ :
خداوند متعال نے سورہ نساء کی آیت ۳۱ میں ارشاد فرمایا : اگر تم ان بڑے بڑے گناہوںسے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کر دیں گے۔
گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنے سے انسان کو ایک قسم کا روحانی تقوا حاصل ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے جن کی وجہ سے انسان گناہان صغیرہ کو پاک کرسکیں ۔ اور یہ آیت تقریبا(
إِنَّ الحْسَنَاتِ يُذْهِبنَْ السَّيَِّات
)
سورہ ہود کی آیت/ ۱۱۴ کی طرح ہے ۔
ہمیں یہاں پر اس نکتہ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ گناہان صغیرہ جب تک صغیرہ ہیں ان کو تکرار نہیں ہونا چاہیے وگر نہ یہ گناہان کبیرہ میں بدل جاتے ہیں ۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَار
گناہ کوتکرار کرنے سے وہ صغیرہ نہیں رہتا ہے ۔
چھوٹے گناہ شیطان کا حیلہ شمار ہوتے ہیں ان کو انسان کی آنکھوں میں چھوٹا کرکے جلوہ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ سے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور انسان پر غلبہ پاتے ہیں ۔
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا :الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ طُرُقٌ إِلَى الْكَبَائِرِ وَ مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ فِي الْقَلِيلِ لَمْ تخفه فِي الْكَثِيرِ
چھوٹے گناہ بڑے راستوں کی طرف جانے کا راستہ ہیں اور جو بھی ان چھوٹے گناہوں سے نہ ڈرے تو وہ بڑ ے گناہوں سے بھی نہیں ڈرے گا ۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے :لَا تَنْظُرُوا إِلَى صِغَرِ الذَّنْبِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى مَنِ اجْتَرَأْتُمْ
.
گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نگاہ نہ کرنا بلکہ اس کی طرف نگاہ کرنا جو اس کے مقابل میں جرات کرکے انجام دیتا ہے ۔
چھبیسواں جزء : صبر
(فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِل لهَُّمْ كَأَنهَُّمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نهََّارِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُون
)۔
پس (اے رسول) صبر کیجیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے (طلب عذاب میں) جلدی نہ کیجیے، جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہو گا گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، (یہ ایک) پیغام ہے، پس ہلاکت میں وہی لوگ جائیں گے جو فاسق ہیں۔
۱۔ صبر پیغمبروں کا طریقہ :
خداوند متعال پیغمبر اسلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح سے صبر کریں حضرت نوح نے تقریبا ۹۵۰ سال عمر کی اوردین کی تبلیغ کی لیکن بعض ایمان لائے ا اور بعض نے ان کا مذاق اڈایا ۔ اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور حضرت موسی اپنی قوم سے فرار ہونے پر مجبور ہوئے اور حضرت عیسی کو بہت ساری اذیتیں دینے کے بعد اس کو سولی پر چڑھایا گیا لیکن انہوں نے ان تمام مشکلات کو عزم و ارادہ سے طے کیا تو اولوالعزم قرار پائے
۲۔ انواع صبر :
صبر کی مختلف انواع ہیں اور پیغمبراسلام ہر نوع پر صابر تھے قرآن مجید نے مختلف پیغمبروں کے مختلف صبرکو بیان کیا ہے ۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے صبر کے مختلف انواع بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔ مصسبت پر صبر کرنا اور اطاعت پر صبر کرنا اور معصیت پر صبرکرنا ہے اور یہ تیسری قسم کا صبر پہلے والے دونو ں سے زیادہ ہی اہم ہے ۔
۳۔ صابرین کی نشانی :
صابر انسان کی کچھ نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تول سکتا ہے وہ کتنا صابر ہے ۔
پیغمبر اسلام نے فرمایا : صابر کے لئے تین نشانیاں ہیں پہلی یہ کہ وہ سست نہیں ہوتا اور دوسری وہ بے قرار نہیں ہوتا اورتیسری وہ خدا سے گلہ و شکوہ نہیں کرتا ۔اگر وہ سست ہو جائے تو اپنے حق کو ضایع کیا اور اگر بے تابی کریں تو گویا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا اور اگر شکایت کرے تو گویا اس نے خدا کی نافرمانی کی
۴۔ صبر کا سر چشمہ :
الف ۔ خداپر یقین رکھنا :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے
۔أَصْلُ الصَّبْرِ حُسْنُ الْيَقِينِ بِاللَّه
۔ صبر کی اصل ریشہ خدا پر نیک یقین رکھنا ہے ۔
ب ۔ شوق و خوف اور بے رغبتی اور انتظار :
پیغمبر اسلام نے صبر کی چار قسموں کو بیان کیا ہے ۔۱ ۔ اشتیاق ۔ ۲۔ خوف ۔ ۳۔ بے رغبتی ۔ ۴۔ انتظار
اگر کوئی بہشت کا مشتاق ہو تو اسے شہوت ترک کرنا چاہیے اور اگر کوئی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے تو وہ حرام کاموں سے اپنے کو بچائے
اور کوئی اس دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے تو وہ دنیا کی مشکلات اور گرفتاریوں کو ہلکا سمجھ لے اور جو مرنے کے انتظار میں میں ہے تو وہ اچھے کاموں کی طرف جلدی کرے
د ۔ جلدی نہ کرنا :
سورہ احقاب کی آیت /۳۵ میں خدا وند متعال نے فرمایا
: (فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِل لهَّم
)۔
پس (اے رسول) صبر کیجیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے (طلب عذاب میں) جلدی نہ کیجیے۔
ھ ۔ آگاہی حاصل کرنا :
حضرت خضر نے حضرت موسی کی جلدی بازی جو ان کے سوالوں کے جواب جاننے کے بارےمیں فرمایا کہ
(قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبرًْا وَ كَيْفَ تَصْبرُِ عَلىَ مَا لَمْ تحُِطْ بِهِ خُبرًْا
).
و ۔ امید :
جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ اپنی توان کو کھو بیھٹتے ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے ۔
(وَ لَا تَهِنُواْوَ لَا تحَْزَنُواْ وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين
)
۔ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو کہ تم ہی غالب رہوگے بشرطیکہ تم مومن ہو۔
ی ۔ صبر کی عادت کرنا :
امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو لکھا کہ
عَوِّدْ نَفْسَكَ الصَّبْرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُرُ فِي الْحَقِّ
اپنے نفس کو ناملائمات کے مقابل میں صبر کی عادت کراو اور حق پر صبر کرنا بہترین اخلاق ہے
ستائیسواں جزء : دنیا سے کٹ جانا ( زہد )
(
مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فىِ الْأَرْضِ وَ لَا فىِ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فىِ كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبرَْأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسِيرٌلِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلىَ مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئكُمْ وَ اللَّهُ لَا يحُِبُّ كلَُّ مخُْتَالٍ فَخُور)
کوئی مصیبت زمین پراور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے یقینا یہ نہایت آسان ہے۔ تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اللہ کسی خودپسند، فخرجتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔
۱ زہد کامل :
خدا وند متعال اس دنیا سے دلگی نہ کرنے کے بارے میں اور اس میں موجود چیزوں پر خوشحال یا غمگین نہ ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے خلق ہونے سے پہلے یہ ساری چیزوں کو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے ۔ مصیبت اور تمام آفات یا گناہوں کے مجازات کے بارے میں
(بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكمُْ
)۔
یاایسی مصیبتیں کہ جن میں انسان کا کوئی نقش و کردار نہیں ہے الا فی کتاب قبل ان نبراھا امتحان کے خاطر یا مقام کے ارتقاء کے لئے ہے ۔ لیکن بات یہ ہے کہ خدانے کیوں ان کو لوح محفوظ پر ثبت کیا ہے ؟ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ
(لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلىَ مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئكُمْ
)۔اس کا ہدف یہ ہے کہ دنیا کے اس زرق و بر ق میں گرفتار نہ ہو جائے ۔
لیکن وہ افراد جو ایماندار ہیں اس دنیا میں کوئی نعمت چھین جانے سے فکرمند نہیں رہنا چاہیے اور آنے سے خوشحال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے سامنے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی لئے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام زہد قرآن کے اندر صرف دو جملوں میں ہے خدانے فرمایا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس پر غمگین نہیں ہونا اور خدانے تمہیں جو دیا ہے اس پر غرور نہ کرنا اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو زہد کامل حاصل ہو جاتا ہے
اور روایت میں حرام سے دوری کرنے کو زہد کا بلند ترین درجہ شمار کیا گیا ہے جیسا کہ پیغمبراسلام کا فرمان ہے ۔الزهد الناس من اجتنب الحرام
۔ لوگوں کا زہد حرام سے اجتناب کرنا ہے ۔
زہد ایسا نہیں کہ انسان حلال خدا کو حرام قرار دے ۔ اور اس دنیا سے الگ ہو کر رہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ حلال و حرام کی تمیز کریں حرام سے بچے رہے اور اس دنیا کو اپنا تکیہ گاہ نہ بنائیں بلکہ خدا کو اپنا تکیہ گا ہ فرض کریں ۔
زہد یہ ہے کہ انسان حرام پر صبر اور حلال پر شکر کرنا نہ بھولیں ۔
۲۔ عوامل زہد :
الف ۔ یقین :
انسان کو ہر چیز سے بے رغبتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کو پتہ چل جائے کہ وہ اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے اسی لئے امام علی علیہ السلام اصل زہد کو یقین جانتے ہیں ۔ اور فرماتے ہیں کہ :زُهْدُ الْمَرْءِ فِيمَا يَفْنَى عَلَى قَدْرِ يَقِينِهِ بِمَا يَبْقَى
۔
انسان کا زہد نابود ہونے والا نہیں ( امور دنیوی ) اور اس کے اندازے کے مطابق باقی رہنے والا ہے ( امور اخروی )
ب۔ موت کو یاد کرنا :
موت کو یاد کرنے سے انسان کو یقین حاصل ہوجاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے باقی رہنے والی نہیں اسوقت کسی اور کی طرف جائے گی اور ایسے چیز سے دلگی کریں گے کہ جو باقی رہنے والی ہو اور اپنے آپ کو اس دنیا کی ہر چیز سے آزاد سمجھے گا اور اس دنیا فانی کو کوئی اہمیت نہیں دے گا ۔اسی بنا پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ۔مَنْ صَوَّرَ الْمَوْتَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ هَانَ أَمْرُ الدُّنْيَا عَلَيْه
جو بھی موت کو اپنے آنکھوں میں تصور رکھے تو اس دنیا کی تمام مشکلات اس پر آسان ہو جائیں گی ۔
پ ۔ دنیا کے نقصان پر توجہ دینا :
امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہأَحَقُ النَّاسِ بِالزَّهَادَةِ مَنْ عَرَفَ نَقْصَ الدُّنْيَا
.
لوگوں میں بہترین زاہد وہ ہے جو دنیا کے نقص کو پہچان لیں ۔
ت ۔ شناخت خدا :
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت موسی خدا کے ساتھ مناجات کررہے تھے تو خدانے فرمایا :
إِنَّ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ زَهِدُوا فِيهَا بِقَدْرِ عِلْمِهِمْ بِي وَ سَائِرُهُمُ مِنْ خَلْقِي رَغِبُوا فِيهَا بِقَدْرِ جَهْلِهِمْ بِي
.
بندگا ن صالح اس دنیا میں ان کے علم کے مطابق زہد اختیار کرتے ہیں اور دوسر ے ان کے جہل کے مطابق اس دنیا کو چاہتے ہیں
ث ۔ آخرت پر توجہ دینا :
امیر المؤمنین کا فرمان ہےكَيْفَ يَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْآخِرَةِ غرر الحکم
جو آخر ت کی ارزش کو نہیں جانتا وہ اس دنیا سے کیسے بے رغبت ہو گا ۔
۳۔ زہد کے آثار :
الف ۔ حکمت کو دل میں پیداکرنا اور زبان پر جاری کرنا :
پیغمبر اسلام نے اباذر کو فرمایا : اگر انسا ن اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے تو خدا وند عالم دنیا میں اس کے دل میں اور زبان سے حکمت جاری کردیتا ہے اس کو دنیا کے تما م عیبوں اور دردوں سے بصیر بنا دے گا اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام تک پہنچ جائے گا
ب۔ ایمان کی مٹھاس کو چکھنا :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ۔ ایمان کی مٹھاس کو پہچاننا آپ پر حرام ہے مگر یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں
پ ۔ نزول رحمت :
امیر المؤمنین کا فرمان ہے :ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا تَنْزِلْ عَلَيْكَ الرَّحْمَة
.
۔دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل ہو جائے ۔
ث ۔ مصیبتوں کا آسان ہو جانا :
امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا :مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُهَا وَ لَمْ يَكْرَهْهَا
.
جب بھی کوئی دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں اور اس کو اذیت نہیں دیتی ہیں ۔
ت۔ فقیر ہونا :
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ۔لَنْ يَفْتَقِرَ مَنْ زَهِدَ
.
جو بھی زہد کو ا پنا پیشہ بنائے تو وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہو گا۔
آٹھائیسواں جزء : خدا کو یاد کرنا
(يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ لْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ.وَ لَا تَكُونُواْ كاَلَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَئهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِقُون
)۔
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل (روز قیامت) کے لیے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ یقینا اس سے خوب با خبر ہے۔
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوںنے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔
۱۔ خدا کو نہیں بھولنا :
قرآن مجید دو گروہوں ( شیطان اور اس کے اتباع کرنے والے ) منافقین اور ان کے پیروی کرنے والے کو دائمی جہنمی قرار دیتا ہے مؤمنین کے ساتھ ہمکاری کرنا رحمت خدا سے دور ہونا ہے خدا وند عالم مؤمنین سے یہی چاہتا ہے کہ خدا کی مخالف کرنے سے پرہیز کریں اور تقوا الہی اختیار کریں اور خداکو بھول نہ جائے تاکہ خدا ان کو بھی نہ بھلا دے
نکتہ : تقوا الہی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ۔ ہر حال میں خدا کو یاد کرنا کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے ۔اور اپنے نامہ اعمال اورخدا کی عدالت کی طرف توجہ دینا ۔ اسی لئے تربیت کے لئے انبیاءاور اولیاء کو بھیجا گیا ہے ۔
۲۔ خدا کو بھول جانے کے آثار :
الف ۔ خود کو بھول جانا :
آیت میں خدا کو بھول جانا خود فراموشی کی وجہ سے جانا ہے چونکہ انسان جب خدا کوبھلا دیتا ہے تودنیا کے لذات میں ڈوب جاتا ہے اورآخر ت کے لئے کوئی چیز زخیرہ نہیں کرسکتے ۔
وہ شخص جو خداکو فراموش کرتاہے آہستہ آہستہ سے خدا کی صفات کو بھی بھول جاتا ہے جیسا کہ قادر مطلق اور تسلط بہ عالم اور علم کامل جیسی صفات کو بھول جاتا ہے اور اپنے کو خدا سے بے نیاز جانتا ہے اپنے فقرکو بھول جاتا ہے اور انسان کے دائرے سے خارج
ہوکر حیوان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے ۔
اسی وجہ سے خداوند متعال آخر میں فرماتے ہیں ۔
(أُوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِقُون
)ایسے لوگ فاسق ہیں ۔
نکتہ : اس آیت میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خدا کو فراموش نہ کرو بلکہ یہ کہہ رہا ہے ان جیسا نہ بنوں کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے اور خدا نے ان کو فراموشی میں مبتلا کیا ہے ۔یہ بہت ہی واضح چیز ہے جو انسان محسوس کر سکتا ہے اور دوسرے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کو فراموش کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
ب۔ اضطراب اور سختی :
خداکو فراموش کرنے کے اہم ترین آثار میں سے ایک انسان کا بے یار ومددگا ر ہونا ہے کہ جس سے انسان اضطراب اور سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن خداوند عالم کا ذکر انسان کے دلوں کو اطمیئنان بخشتا ہے ۔جیسا کہ فرمایا :
(
الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَئنُِّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوب
)
.
۔(یہ لوگ ہیں) جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل یادِ خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور یاد رکھو! یاد خداسے دلوںکو اطمینان ملتا ہے۔
اضطراب کی مختلف علتیں ہیں ۔۱۔ انسان کے گزشتہ گناہ اور لغزش وغیرہ سے مضطرب ہو سکتا ہے ۔۲۔ دشمنوں کے سامنے ضعیف اور ناتوان ہونے کی وجہ ے ۔۳۔ زندگی کو بے ہدف اور بے مقصد جاننے کی وجہ سے ۔۴۔ اس کی تلاش وکوشش پر لوگوں کی ناشکری کا احساس کرنا ۔ ۵ ۔ اس دنیا کے زرق برق پر دل لگانا یا مرنے سے ڈر کی وجہ سے ۔۔ یہ خدا کو فراموش کرنے کے بعض آثار ہیں جو انسان کی زندگی تنگ او راضطراب کا سبب بنتا ہے ۔(
وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا
)
.
اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقینا ایک تنگ زندگی نصیب ہو گی ۔
یہاں پر سخت زندگی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اپنے خدا کو بھول جاتا ہے تو اس زندگی میں اس کو ئی اور راستہ نہیں رہتاہے سوای اس کے کہ اس دنیا کو طلب کرے اور اس کو حاصل کرنے کی تلاش کرے اس قسم کے بندوں کی زندگی میں یا زیادہ ہو یا کم ہو وہ پھر بھی اس کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے ۔ چونکہ جو بھی وہ حاصل کرتا ہے اس کو صرف اضطراب اور پریشانی غم واندوہ میں مبتلا ہو جاتا ہے
اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالدُّنْيَا تَعَلَّقَ مِنْهَا بِثَلَاثِ خِصَالٍ هَمٍّ لَا يَفْنَى وَ أَمَلٍ لَا يُدْرَكُ وَ رَجَاءٍ لَا يُنَالُ
.
۔جو بھی دنیا کے ساتھ دل لگائے گا وہ تین بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گا ۔۱ غصہ اور پریشانی میں ۔ ۲۔ لمبی آرزوئیں کرنے لگے گا ۔ ۳۔ ایسی امید رکھے گا جو کبھی بھی حاصل نہیں ہو گی ۔
پ ۔ گناہوں سے آلودگی :
خداکو بھول جانا ایک ایسا عامل ہے کہ شیطان سے انس و دوستی اور گناہوں میں آلودہ ہونے کا سبب بنتا ہے ۔
(وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاوَ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين
)۔
اور جو بھی رحمن کے ذکر سے پہلوتہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
خدا کو یاد کرنے سےمراد صرف زبان پر بولنا نہیں ہے بلکہ اپنی تمام وجود کے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ گناہ کا دروازہ محکم بند ہو جائے اسی لئے پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین کو وصیت کی ہے کہ اے علی تین کا م ایسے ہیں جومیری امت تحمل نہیں کرسکتی ۔
۱۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ مال میں مساواۃ رکھنا ۔
۲۔ لوگوں کے حق کو ادا اور یاد خدا کرنا۔
۳۔ خدا کا ذکر فقط زبان پر
سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا الهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرْ
کہنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کے سامنے روبرو تو خو ف خدا سے گناہوں کو ترک کردے
روایت میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کیا گناہ سے بچنے کے لئے کوئی راستہ بتائیں
تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا : پانچ کام کرو اور جو چاہے گناہ کرواطْلُبْ مَوْضِعاً لَا يَرَاكَ اللَّهُ وَ أَذْنِب
ایک ایسی جگہ پر جاکر گناہ کرو کہ جہاں پر خدا آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو ۔
ث ۔ سخت دل :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے خدا کو فراموش کرنے کا اثر یہ ہے کہ قساوت قلبی ہو جاتی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا وند متعال کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور سنگ دل شخص خدا سے دور رہتا ہے
پ ۔ قیامت کے دن نابینا ہونا :
جو شخص خدا کی یاد سے غفلت کرے تو وہ بصیرت اور تیز بینی کو کھو دیتا ہے اور قیامت کے دن ناببنا محشور ہو گا ۔
(وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَ نحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى
)
. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقینا ایک تنگ زندگی نصیب ہو گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔
انتیسواں جزء :اخلاق برجستہ
(وَ إِنَّكَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِيم
).
۔ اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔
۱۔ اخلاق عظیم پیغمبر :
یہ آیت پیغمبر اکرم کی عظیم صفات کے بارے میں بیان کررہی کہ ہے آپ صاحب علم ہیں اور برجستہ اخلاق کا مالک اور آپ کا لطف و کرم بے نظیر ہے جب آپ تبلیغ کرتے تھے تو پہلے خود اسے انجام دیتے تھے اور عمل کرتے تھے پھر لوگوں کو بتاتے تھے نیکی پہلے خود انجام دیتے تھے پھر لوگوں کو بتاتے تھے جب لوگ آپ کو پتھر مار کر اذیتیں دیتے تھے تو گھر آکر ان کے حق میں دعا کرتے تھے ۔
خلق مادہ خلقت سے ہے یہ صفت کے معنی ہے جو انسان سے کبھی جدا ہونے والی نہیں ہے پیغمبر اکرم کے صفات میں سے صرف خلق عظیم ہی نہیں بلکہ دعوت حق میں صبر اور سختیوں پر تحمل کرنا اور خدا کی راہ میں عفو و درگزر اور جہاد وغیرہ بھی پیغمبر کے صفات میں ہیں لیکن خلق عظیم اس پر منحصر نہیں ہے ۔
۲۔ اخلاق پیغمبر کا ایک نمونہ :
پیغمبر اسلام کے اخلاق کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کا اخلاق اس کے ساتھ ہم نشینوں کے لئے اس طرح تھا کہ خوش اخلاق اور خوش رو اچھے اخلاق اور نرم مزاج تھے ہرگز غصہ نہیں کرتے تھے بدزبان اور عیب جو اور بے جا مدح کرنے والے نہیں تھے اور کوئی بھی ان سے مایوس نہیں ہوتے تھے او رجو بھی ان کے گھر آتے تھے ناامید نہیں جاتے ۔
اور تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے سے دور کرتے تھے بات کرنے میں مجادلہ کرنا زیادہ باتیں کرنا اور جو کام ان سے مربوط نہیں ہوتا اس میں دخالت نہیں کرتے تھے اور اسی طرح سے تیں چیزوں کو لوگوں کی خاطر اپنایا تھا کسی کی مذمت اور سرزنش نہیں کرتے تھے
اور دوسروں کی عیب جوئی کرنے کی جستجو نہیں کرتے تھے اور اسوقت تک بات نہیں کرتے جب تک بات کرنے میں خدا کی
طرف سے کوئی اجازت نہ ہوتی اور جب بات کرتے تو بھی ان کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ سارے لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے تھے ۔
اور اس کے سامنے کبھی بھی مجادلہ نہیں کرتے تھے ۔ اور جب بھی کوئی انجان بندہ سختی کے ساتھ بات کرتا تو وہ تحمل کرتے تھے اور اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ جب بھی کسی محتاج کو دیکھیں تو اس کو دے دیں اور کبھی کسی کی قطع کلامی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی باتوں کو ختم کرے
پیغمبر اسلام کی رسالت کا مقصد و ہدف خود پیغمبر کی زبان میں مکارم اخلاق کو بیان کیا ہےإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق
.
مجھے مکارم اخلاق کو اکمال تک پہنچانے کے لئے بھیجا گیا ہے ۔
۳۔ حسن خلق کے آثار :
الف ۔ ایمان کا قوی ہونا :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے جب خداوند عالم نے ایمان کو خلق کیا تو ایمان نے عر ض کیا اے خدا مجھے قوت دے تو خدا وند عالم نے اسے اچھے اخلاق اور سخاوت کے ساتھ تقویت دی
اور جب کفر کو خلق کیا تو عرض کیا اے خدا مجھے قوت دے تو خدا نے اسے بخل اور برے اخلاق سے تقویت دی ۔
ب ۔ عزت بخشی :
امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ ان کے اخلاق ان کو خوار کرتا ہے اور بہت سارے خوار انسان کو ان کے اخلاق انکو عزیز بناتا ہے
پ ۔ جہنم کی آگ سے دوری :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہمَا حَسَّنَ اللَّهُ خَلْقَ امْرِئٍ وَ خُلُقَهُ فَيُطْعِمَهُ النَّار
.
خدا کسی کے اخلاق کو اچھا نہیں کرتاہے کہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہو ۔
ت۔ لوگوں کے درمیان زندگی کا امکان :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے تین چیزیں جس شخص میں نہ ہو تو وہ شخص خدا اور مجھ سے نہیں سؤال کیا یا رسول اللہ وہ کونسی تین چیزیں ہیں تو فرمایا : علم کے ذریعے سے جہل کو دور کریں اور لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں اور تقوا اختیار کریں تاکہ معصیت سے بچ جائیں
چ ۔ رسول کا ہم نشین :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین انسان وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو گا ۔
ح ۔ حرام سے دوری :
امیر المؤمنین کا فرمان ہےمِنْ أَحْسَنِ الْمَكَارِمِ تَجَنُّبُ الْمَحَارِم
.جس کا بھی اخلاق اچھا ہو وہ حرام سے دور رہتا ہے ۔
خ ۔ آبادی اور عمر کا بڑھ جانا :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ۔إِنَ الْبِرَّ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ
.
نیکی اور اچھا اخلاق شہروں کو آباد اور عمر کو طولانی کرتا ہے ۔
د ۔ خطا کی نابودی :
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے نیک اخلا ق خطاؤں کو ختم کرتا ہے جس طرح سے سورج کی گرمی سے برف پگل جاتی ہے اسی طرح اچھا اخلاق انسان کی خطاؤں کو پگھلا دیتا ہے ۔
ذ۔ مودت اور علاقہ کا ثابت رہنا
پیغمبر اسلام کا فرمان ہےحُسْنُ الْخُلُقِ يُثْبِتُ الْمَوَدَّة
.
اچھا اخلاق مودت کو ثابت کرتا ہے ۔
اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ نیک اخلاق کے لئے عقل سے استفادہ کرنا بہترین عامل شمار ہوتا ہے ۔ اسی لئے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیںالْخُلُقُ الْمَحْمُودُ مِنْ ثِمَارِ الْعَقْلِ و لْخُلُقُ الْمَذْمُومُ مِنْ ثِمَارِ الْجَهْل
.
بہترین اخلاق کا ثمرہ عقل ہے اور بد ترین اخلاق کا ثمرہ جہل ہے
تیسواں جزء حسادت
(وَ مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد
)
.اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے ۔
۱۔ شَرّ حسد :
خدا وند متعال نے اس سورہ کی ابتدا میں پیغمبر اسلام کو حکم دیا ہے کہ کہدیجیے: میں ہر صبح اور شام کے رب سے پناہ مانگتا ہوں ،
اور ان شریروں کے شر سے جو رات کو لوگوں پر حملہ کرکے قتل کرتے ہیں اور حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو معاشرے کو خراب کرنے اورفساد کرنے کے ایک عمدہ ترین عامل شمار ہوتے ہیں ۔
سورہ کی ابتدا میں خدا کی جو صفات بیان ہوئی ( برب الفلق ) اس سے ممکن ہے اس نکتہ کی طرف اشارہ کریں کہ تین گروہ ایسے ہیں جو ہمیشہ تاریکی اورجہل و اختلاف اورکفر سے استفادہ کرتے ہیں اگر یہ تاریکی علم کی روشنائی میں اوراتحاد و ایمان میں تبدیل ہو جائے تو ان کا یہ حربہ سست ہو جائے گا
حسد دوسروں کو نعمت سے درو کرنے کی آرزو ہے کہ قرآن مجید میں بہت ہی سختی کے ساتھ اس سے منع ہوا ہے اور کونسی نعمت تہذیب اور خود سازی سے بڑھ کر ہے اور وہ بھی جب روزہ داری میں ہو اسی لئے اس ہوشیاری کو جدی لے لیں کہ شیطان اور شیطان صفت ان روزہ داروں کے بارے میں زیادہ حسد کرتے ہیں تاکہ اس ایک مہینہ روزہ رکھنے میں ان کو جو نعمت مل جاتی ہے اور اس سے چھین لے اور ان کو اسی حالت پر نہ چھوڑیں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ۔اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا يَحْسُدْ بَعْضُكُمْ بَعْضا
تقوا اختیار کرنا اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا ۔
امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک مبغوض ترین انسان وہ ہے جو ریاست طلب ہو اور سخن چینی کرتے ہوں اور اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہوں ایسے لوگ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں خدا کی قسم اگر آپ میں سے کوئی اس زمین کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے مومن بھائی کے لئے رشک کرے اور بد خواہ ہو جائے تو وہ سونا جہنم کی آگ کو زیادہ کریگا
اور امیر المؤمنین حسد کو تمام خرابیوں کا جڑ اور تمام بیماریوں کا شر سمجھتے ہیں ۔
۲۔ حسد کی انواع اور اقسام :
الف ۔ حسد شخصی :
اور آپ انہیں آدم کے بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا: میں تجھے ضرور قتل کروں گا،
ب۔ حسد سیاسی :
کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی
اور امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا :نحن المحسودون
۔ کہ ہم مورد حسد قرار پائے ہیں ۔
ج ۔ حسد دینی :
اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے یہ آرزو کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان اور اسلام سے کفر کی طرف لوٹا دے اس کے باوجود کہ حق ان کے لئے واضح ہو گیا ہے
۳۔ حسد کے آثار :
الف ۔ ایمان کی نابودی :
امام محمد باقر علی السلام کا فرمان ہے
إِنَ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ
.
حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے ۔
ب۔ قتل :
حسد جنایات کے اہم ترین عامل میں سے ہے جہاں سے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل قابیل کی حسادت کی وجہ سے ہوا ہے اور حضرت یوسف کو اسی حسد کی بناپر اس کو کویں میں ڈالا گیا
ت ۔ آرامش کا ختم ہونا :
حسد کرنے والا ہمیشہ روحی مریض رہتا ہے اور اس کا سکون اس سے چھین لیا جاتا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ۔
أَسْوَأُ النَّاسِ عَيْشاً الْحَسُودُ
.
بدترین لوگ زندگی میں حسد کرنے والے ہیں۔
ث۔ دوستوں کا ہاتھ سے نکل جانا :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ۔الْحَسُودُ لَا خُلَّةَ لَه.
۔حسد کرنے والے کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے ۔
الْحَسُودُ لَا يَسُودُ
.
حسد کرنے والا کبھی نفع نہیں اٹھا سکتا ہے ۔
ز ۔ گناہ میں اضافہ ہونا :
الْحَسُودُ كَثِيرُ الْحَسَرَاتِ مُتَضَاعِفُ السَّيِّئَاتِ
.
حسد کرنے والے زیادہ حسر ت کرتے ہیں اور اس میں اس کے گناہ میں اضافہ ہوجاتا ہے ۔
۴۔ حسد کے عوامل ۔
الف ۔ کینہ اور عداوت :
دوسروں سے دشمنی رکھنے میں انسان کو دوسروں کے مال و دولت اور علم اور ان کی موفقیت کو نہیں دیکھ سکتا ہے اور اپنی شکست سمجھتا ہے اسی لئے سے یہ نعمت چھیننے کی خاطر خود کو آگ لگاتاہے اور یہی حسادت شیطان ہے ۔
ب۔ خود کو بڑا سمجھنا :
انسان جب اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو دوسروں کو دیکھنے کے لائق ہی نہیں سمجھتا اسی بنا پر دوسروں کے مادی اور معنوی نعمات پر حسد کرنے لگتا ہے اور صرف اپنے کو ہی لائق سمجھتا ہے کہ شیطان بھی اسی تکبر کی وجہ سے حسد کرنے لگا ۔
پ ۔ ریاست طلبی :
انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو چھین لے تاکہ خود کو ریاست کی کرسی مل جائے اور دوسروں پر حاوی رہے بہت سارے حسد سیاسی حسد مذہبی حسد اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ۔
ت۔ حقارت اور ناکامی :
انسان جب شکست کھاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی کامیابی کو پسند نہیں کرتا ہے اور آرزو رکھتا ہے کہ کاش دوسرے بھی اسی کی طرح شکست کھاتے بجائے اس کے کہ اپنی شکست کا جبران کریں دوسروں کو بھی اس شکست کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اور جب خود حقیر ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسر ے بھی اس کی طرح حقیر بن جائیں ۔
ث ۔ بخل :
انسان بخیل نہیں ہوتا ہے جب اپنے مال کو دوسروں کے اختیار میں رکھے اور جب نعمت دوسروں تک پہنچتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ تنگ نظری اور خباثت و رذالت انسان کو حسد کی طرف کھینچ لیتی ہے ۔
ج ۔ قدرت خدا پر ایمان نہ رکھنا :
اگر انسان یہ قبول نہ کرے کہ خداوند عالم نے اپنی قدرت سے ان نعمتوں کو دوسروں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے اور اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوئے ہیں اس کا حق دوسروں سے زیادہ ہوناچاہیے اور دوسروں کے لئے کم ہونا چاہیے اسی لئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسی کو وحی ہوئی ۔
میں نے اپنے فضل وکرم سے جو لوگوں کو دیا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی حسد نہ کریں اور اپنے دل میں ان کے بارے میں نہ سوچیں کیونکہ جو میری اس تقسیم بندی پر اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی حسد کی وجہ سے ہے اگر کوئی اس طرح کا حسد کرے گا تو میں اس میں سے نہیں اور وہ مجھ سے نہیں ہے
۴۔ حسد کا علاج :
الف ۔ حسد کے مضرات کے بارے میں فکر کرنا :
وہ انسان جو ہمیشہ اپنے نفع کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اس کے لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اس حسد سے حاصل ہونے والے مضرات کے بارےمیں فکر کریں اور یہ قبول کریں کہ اس میں اسی کا فائدہ ہے کہ اس حسد کو ترک کریں لذا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : حسد کرنے والے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے پہلے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے ۔ اور ابلیس کی طرح جو اپنے حسد کی وجہ سے تاآخر لعنت کا حقدار بن گیا اور حضرت آدم کو ہدایت کا راستہ فراہم کیا
ب۔ حسد کا غبطہ میں بدل جانا :
انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں سے نعمت کے سلب ہونے کی آرزو کرنے سے( حسد )خود اپنے اندر یہ روحیہ پیدا کریں کہ وہ نعمت اپنے لئے بھی چاہے اور اس کی تمنا کریں ( غبطہ )۔
پ ۔ عملی جنگ :
انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر جو حسد کی بیماری ہے اس کا عملی طور پر علاج کرائے اور اپنے اندر موجود اس حسد کو ختم کرے اور اس کے ساتھ جنگ کرے اور حسد کی جو حس انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اس پر عمل نہ کرے ۔
اسی لئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغ.
جب حسد پیدا ہو جائے تو اس پر عمل نہ کرو ۔
ت ۔ عملی میدان میں حسد کو پیچھے چھوڑنا :
حسد کے مختلف مراحل ہیں ۔ ۱۔ دل میں حسد ۔ ۲۔ اندرونی حسد جو کہ کنٹرول سے باہر ہے ۔ انسان اس حسد کو مرحلہ عملی سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی مرحلہ قلبی میں ہی اس پر کنٹرول کرنا چاہیے ۔
ث ۔ کامیابی :
بہت ساری حقارتیں اور دوسروں کو تحمل نہ کرنا اور ان کے پاس موجود چیزیں ان شکستوں کی وجہ سے ہیں جو حاسدوں نے تجربہ کیا ہے پس ان کو دکھانا چاہیے کہ خطا اور اشتباہ کے جبران کے لئے ہمیشہ ایک راستہ ہے نہ کہ فقط دوسروں سے نعمت کا سلب ہونا اور یہ منطق چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو دوسروں کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے کہنا ایک فضول منطق ہے اگر اسی پر عمل کیا جائے تو پھر معاشر ے میں پورا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا ۔
ج ۔ تکبر اور بڑھائی :
اے کا ش کہ یہ عداوتیں اور ریاست طلبی کی بجائے دوسروں کی خدمت کرنے کی جوحس ہے اس کی تقویت ۔اور بہت سارے ایسے راستے جو اس حسادت کو کم کرنے کےلئے اسکے اندر موجود ہوتے ہیں ۔
چ ۔ رضایت :
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہمَنْ رَضِيَ بِحَالِهِ لَمْ يَعْتَوِرْهُ الْحَسَدُ
.
جو چیزیں انسان کے پاس موجود ہو اگر اسی پر راضی ہو جائے تو وہ کبھی بھی حسد نہیں کرتاہے ۔
ح۔ خدا کی عدالت پر ایمان :
حسد کرنے والے کو یہ معرفت ہونی چاہیے کہ خداوند عالم کے سارے کام میں حساب وکتاب ہے اور حکمت و عدالت ہے لذا انسان اپنی حسادت کی وجہ سے خدا کی عدالت اور حکمت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ۔
تمّت بالخير
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعالَمين
____________________
 0%
0%
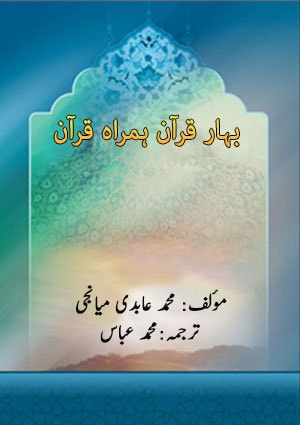 مؤلف: محمد عابدی میانجی
مؤلف: محمد عابدی میانجی