البیان فی تفسیر القرآن
 8%
8%
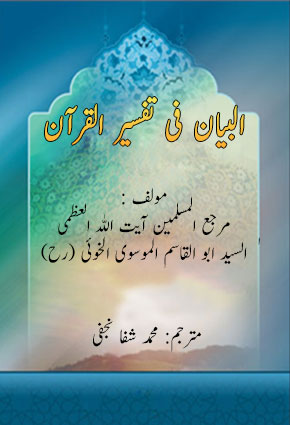 مؤلف: آیت اللہ العظمی سید ابوالقاسم الخوئی رح
مؤلف: آیت اللہ العظمی سید ابوالقاسم الخوئی رح
زمرہ جات: تفسیر قرآن
صفحے: 689
- عرض مترجم
- مقدمہ
- البیان فی تفسیر القرآن
- قرآنی مکتب
- فضائل قرآن
- تلاوت قرآن کے آداب اور اس کا ثواب
- تلاوت قرآن کی فضیلت اور اس کا ثواب
- گھروں میں تلاوت کے آثار جو روایات میں مذکورہ ہیں
- قرآن میں غور و خوض اور اس کی تفسیر
- اعجاز قرآن
- اعجاز کے معنی
- نبی یا امام معصوم کی نظر میں محال ہونے کی مثال
- نبوّت اور اعجاز
- معجزہ اور عصری تقاضے
- قرآن۔۔۔ایک الہٰی معجزہ
- ایک اعتراض اور اسکا جواب
- قرآن۔۔۔ایک ابدی معجزہ
- قرآن اور معارف
- آیات میں ہم آہنگی
- قرآن اور نظام قانون
- قرآن کے معانی میں پختگی
- قرآن کی غیب گوئی
- قرآن اور اسرار خلقت
- اعجازِ قُرآن اور اوہام
- پہلا اعتراض
- جواب
- دوسرا اعتراض
- جواب
- تیسرا اعتراض
- جواب
- چوتھا اعتراض
- جواب
- پانچواں اعتراض
- جواب
- چھٹا اعتراض
- جواب
- ساتواں اعتراض
- جواب
- آٹھواں اعتراض
- جواب
- نواں اعتراض
- جواب
- قرآن کا مقابلہ
- رسُول اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم)کےدیگر معجزات
- تورات و انجیل میں نبوت محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کی بشارت
- جواب
- جواب
- جواب
- تورات و انجیل میں نبوّت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی بشارت
- قاریوں پر ایک نظر
- تمہید
- ۱۔ عبد اللہ بن عامر دمشقی
- ۲۔ ابن کثیر مکّی
- ۳۔ عاصم بن بہدلہ کوفی
- ۴۔ ابو عمرو بصری
- ۵۔ حمزہ کوفی
- ۶۔ نافع مدنی
- ۷۔ کسائی کوفی
- ۸۔ خلف بن ہشام بزار
- ۹۔ یعقوب بن اسحاق
- ۱۰۔ یزید بن قعقاع
- قراءتوں پر ایک نظر
- تواتر قراءت کے منکرین کی تصریح
- تواتر قراءت کے دلائل
- جواب
- جواب
- جواب
- تتمہ
- قراءتیں اور سات اسلوب
- ۱۔ حجیت قراءت
- جواب
- جواب
- ۲۔ نماز میں ان قراءتوں کا پڑھنا جائز ہے
- کیا قرآن سات حروف پر نازل ہوا؟
- i ۔ ان روایات کے کمزور پہلو
- ii ۔ روایات میں تضاد
- سات حروف کی تاویل و توجیہ
- ۱۔ قریب المعنی الفاظ
- ۲۔ سات ابواب
- ۳۔ سات ابواب کا ایک اور معنی
- ۴۔ فصیح لغات
- ۵۔ قبیلہ ئ مضر کی لُغت
- ۶۔ قراءتوں میں اختلاف
- جواب
- ۷۔ اختلاف قراءت کا ایک اور معنی
- جواب
- ۸۔ اکائیوں کی کثرت
- جواب
- ۹۔ سات قراءتیں
- جواب
- ۱۰۔ مختلف لہجے
- جواب
- مسئلہ تحریف قرآن
- ۱۔ معنی تحریف کی تعریف
- ۲۔ تحریف کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ
- ۳۔ نسخ تلاوت
- تحریف، قرآن کی نظر میں
- تحریف اور سنت
- نماز میں سورتوں کی اجازت
- خلفاء پر تحریف کا الزام
- قائلین تحریف کے شبہات
- پہلا شبہ
- جواب
- دوسرا شبہ
- جواب
- تیسرا شبہ
- جواب
- وضاحت
- روایات تحریف
- روایات کا حقیقی مفہوم
- جواب
- جواب
- چوتھا شبہ
- جمع قرآن کے بارے میں نظریات
- جواب
- جمع قرآن کی روایات
- ۱۔ جمع قرآن کی احادیث میں تضاد
- ٭ قرآن کو مصحف کی صورت میں کب جمع کیا گیا۔
- ٭ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع قرآن کی ذمہ داری کس نے لی ؟
- ٭ کیا جمع قرآن کا کام زید کے سپرد کیا گیا تھا؟
- ٭ کیا حضرت عثمان کے زمانے تک ایسی آیات باقی تھیں جن کی تدوین نہیں کی گئی؟
- ٭ جمع قرآن میں حضرت عثمان کا ماخذ و مدرک کیا تھا؟
- ٭ حضرت ابوبکر سے جمع قرآن کا مطالبہ کس نے کیا؟
- ٭قرآن جمع کر کے اس کے نسخے دوسرے شہروں میں کس نے بھیجے؟
- ٭ دو آئتوں کو سورہ برائت کے آخر میں کب ملایا گیا؟
- ٭ ان دو آئتوں کو کس نے پیش کیا؟
- ٭ یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ دونوں آئتیں قرآن کا حصہ ہیں؟
- ٭قرآن کی کتابت اور املاء کے لئے حضرت عثمان نے کس کا تقرر کیا؟
- ۲۔ روایات جمع قرآن میں تضادات
- ۳۔ احادیث جمع قرآن ، کتاب الٰہی سے متعارض ہیں۔
- ۴۔ احادیث جمع قرآن حکم عقل کے خلاف ہیں۔
- ۵۔ احادیث جمع قرآن خلاف اجماع ہیں۔
- ۶۔ احادیث جمع قرآن اور قرآن میں زیادتی
- نتیجہ
- ظواھر قرآن کی حجیت
- ظواہر قرآن کے حجت نہ ہونے کے دلائل
- ۱۔ قرآن فہمی کا مختص ہونا
- جواب
- ۲۔ تفسیر بالرائے کی ممانعت
- جواب
- ۳۔ معانی قرآن کی پیچیدگی
- جواب
- ۴۔ خلاف ظاہر کا یقین
- جواب
- ۵۔ متشابہ پر عمل کی ممانعت
- جواب
- ۶۔قرآن میں تحریف
- جواب
- قرآن میں نسخ
- نسخ کا لغوی معنی
- نسخ کا اصطلاحی معنی
- نسخ کاامکان
- خلاصہ شبہ
- جواب
- تورات میں نسخ
- شریعت اسلام میں نسخ
- ۱۔ تلاوت نسخ ہو حکم باقی رہے(۱)
- ۲۔ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں
- ۳۔ حکم منسوخ ہو۔ تلاوت باقی رہے۔
- اس مسئلے کی وضاحت
- متعہ کی سزا۔۔۔۔۔۔سنگساری
- متعہ کے بارے میں چند بے بنیادشبہات
- ایک اشکال اور اس کا جواب
- مسلمانوں سے برسر پیکار کفار کے احکام
- آیت کے بارے میں بعض دیگر عقائد
- آیہ نجویٰ پر عمل کی احادیث
- مسئلے کی تحقیق
- اس صدقے کے نسخ ہونے کے اسباب
- حکم صدقہ کی حکمت
- کھلم کھلا تعصّب
- عالم خلقت میں بدائ
- تمہید
- قدرت خدا ۔ یہود کی نظر میں
- بداء شیعوں کی نظر میں
- قضائے الہٰی کی قسمیں
- عقیدہ ئ بداء کے ثمرات
- حقیقت بداء شیعوں کی نظر میں
- اصول تفسیر
- مدارک تفسیر
- خبر واحد سے قرآن کی تخصیص
- چندتوہمات اور ان کاازالہ
- قرآن حادث ہے قدیم
- یونانی فلسفہ کا مسلمانوں کی زندگی پر اثر
- اللہ کی صفات ذاتی و فعلی
- کلام نفسی
- کیا ''طلب ،، کلام نفسی ہے؟
- کلام نفسی کا کوئی وجود نہیں
- کلام نفسی پر اشاعرہ کے دلائل
- تفسیر سورہ فاتحہ
- مقام نزول
- سورہ فاتحہ کے فضائل
- فاتحتہ الکتاب کی آیات
- سورۃ فاتحہ کے اغراض و مقاصد
- سورۃ فاتحہ کا خلاصہ
- بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔کی تحلیل
- لغت
- اعراب
- تفسیر
- آیہ ''بسم اللہ ،، کے بارے میں بحث اول
- آغاز قرآن بہ رحمت
- بعد از رحمن ذکر رحیم
- کیا بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے؟
- بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کے دلائل
- (۱) اہل بیت اطہار (ع) کی احادیث
- (۲) اہل سنت کی احادیث
- معارض روایات
- جواب
- (۳) سیرت مسلمین
- (۴) تابعین اور صحابہ کا قرآن
- منکرین کے دلائل
- تحلیل آیتہ
- قرات
- قراتوں کی ترجیحات
- ترجیحات کابے فائدہ ہونا
- دوسروں کا جواب
- الحمد
- الرب
- العالم
- الملک
- الدین
- تفسیر
- تحلیل آیت
- لغت
- العبادۃ
- الاستعانتہ
- اعراب
- آیتہ ''الحمد،، کے بارے میں بحث دوم
- العبادۃ و التالہ
- عبادت اور اطاعت
- عبادت اور خشوع
- غیر اللہ کو سجدہ
- آدم (ع) کوسجدہ ۔ اقوال علمائ
- شرک باللہ کیا ہے ؟
- اسباب عبادت
- صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا
- شفاعت
- امامیہ کے نزدیک شفاعت کی احادیث
- اہلسنت کے نزدیک شفاعت کی احادیث
- تحلیل آیت
- قرات
- لغت
- اعراب
- تفسیر
- ضمیمہ جات
- ضمیمہ (۱) ص ۱۸
- حدیث ثقلین کے مدارک اور حوالے
- ضمیمہ (۲) ص ۱۸
- حارث کی سوانح حیات اور
- ضمیمہ (۳) ص ۲۰
- حدیث شریف ''لترکبن سنن من قبلکم ،، کے حوالے
- ضمیمہ (۴) ص ۴۳
- مولف اور یہودی عالم میں بحث
- ضمیمہ (۵) ص ۴۳
- ترجمہ قرآن اور اس کی شرائط
- ضمیمہ (۶) ص ۱۱۳
- رسول (ص) اسلام کو شکست دینے کی قریشیوں کی کوشش
- ضمیمہ (۷) ص ۳۱۵
- صحیح بخاری میں حدیث متعہ کی تحریف
- ضمیمہ (۸) ص ۳۲۸
- محمد عبدہ اور تین طلاقیں
- ضمیمہ (۹) ص ۳۸۳
- شیعوں پر رازی کا افترائ
- ضمیمہ (۱۰) ص ۳۹۴
- احادیث اور مشیّت الٰہی
- ضمیمہ (۱۱) ص ۳۹۱
- دعا سے تقدیر الٰہی بدل جانے کی احادیث
- ضمیمہ (۱۲) ص ۲۳۵
- آیہ بسم اللہ کی اہمیت
- ضمیمہ (۱۳) ص ۴۳۶
- آغاز آفرنیش
- ضمیمہ (۱۴) ص ۴۴۶
- بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کی احادیث
- ضمیمہ (۱۵) ص ۴۴۶
- معاویہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا تھا
- ضمیمہ (۱۶) ص ۴۴۶
- رسول (ص) خدا کا بسم اللہ کو پڑھنا اور روایت انس کی توجیہ
- ضمیمہ (۱۷) ص ۴۷۵
- ابن تیمیہ اور زیارت قبور کے جواز کی حدیثیں
- ضمیمہ (۱۸) ص ۴۷۷
- آلوسی کی شیعوں پر بہتان تراشی
- ضمیمہ (۱۹) ص ۴۷۷
- مولف اور حجازی عالم میں بحث
- ضمیمہ (۲۰) ص ۴۷۷
- تربت سید الشہداء کی فضیلت
- ضمیمہ (۲۱) ص ۴۷۹
- مکاشفہ کے ذریعے آیہ سجود کی تاویل
- ضمیمہ (۲۲) ص ۴۷۹
- ابلیس اور خدا کا مکالمہ
- ضمیمہ (۲۳) ص ۴۸۰
- اسلام اور شہادتیں
- ضمیمہ (۲۴) ص ۴۸۲
- عبادت اور اس کے عوامل
- ضمیمہ (۲۵) ص ۴۸۴
- الامربین الامرین : لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں
- ضمیمہ (۲۶) ص ۴۸۷
- شفاعت کے مدارک






