اسلامی مذاهب کی نظر میں فقهی منابع استنباط
 0%
0%
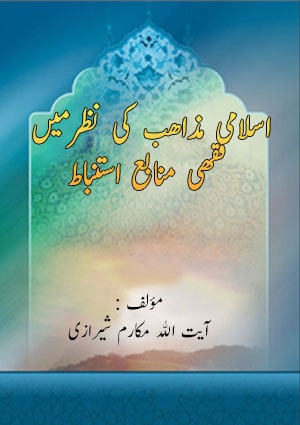 مؤلف: آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی مدظلہ العالی
مؤلف: آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی مدظلہ العالی
زمرہ جات: اصول فقہ مقارن
صفحے: 152
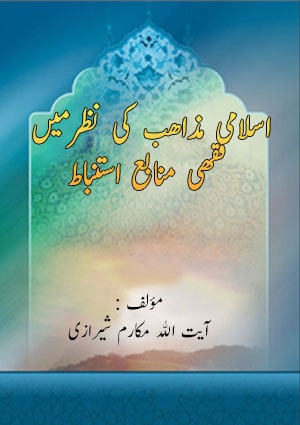
مؤلف: آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی مدظلہ العالی
زمرہ جات:
مشاہدے: 93612
ڈاؤنلوڈ: 5064
تبصرے:
- اہداء
- اظہار تشکر
- عرض مترجم
- چكيده
- 1ـ قرآن
- 2ـ سنت
- 3ـ اجماع
- 4ـ عقل
- منابع مورد اختلاف
- قياس
- استحسان
- سد و فتح ذرايع
- عرف
- مقدمه
- استنباط
- استنباط کے لغوی معنی
- استباط کے اصطلاحی معنی
- استنباط کا تاریخچه
- سنی مکتب
- مقدمات استنباط
- فقهای شیعه کے نظریات
- مقدمات استنباط اہل سنت کی نظر میں
- استنباط کے تکمیلی شرائط
- ضرورت استنباط
- خاتمیت
- احکام اسلامی اور اس کے اہداف کا کلی ہونا
- جاودانگی اسلام
- اسلام کا جهانی ہونا
- جامعیت
- استنباط اصحاب کو استنباط کی تعلیم
- خثعمیه کا رسول خد(ص)سےسوال اور اس کاجواب
- حضرت علی کے کلام میں استنباط کی تعلیم
- امام صادق نے استنباط کے شیوه کو بیان کیا ہے
- شبهات
- استنباط کے شبهات
- استنباط میں افراط و تفریط
- استنباط کو لاحق خطرسےبچانا
- 1- قرآن سے دوری
- قرآن سے دوری کئی خطرات کاباعث ہے
- الف : آیات الاحکام کا محدود کرنا
- ب: ظهور قرآن پر روایت کا مقدم کرنا
- 2- احتیاط کے سلسلے میں فردی نگاہ
- 3- فردی استنباط
- 4- فهم و تفسیر نص میں جمود کا ہونا
- 6- عوام زدگی
- 7- فقیه مقارن پر توجه دینا
- 8- زمان سے دوری اور پرانے مسائل کو پیش کرنا
- استنباط میں زمان و مکان کی تاثیر
- تمهید
- چند اہم نکات
- پهلانکته
- دوسرا نکته
- تیسرا نکته
- توضیح
- "فریقین کے مورد اتفاق منابع استباط ”
- الف: قرآن
- 1 - قرآن کی تعریف
- 3 - دین و شریعت کی شناخت میں قرآن کی مرجعیت
- قرآن الله کا کلام ہے
- 3- موجوده قرآن کی حجیت
- عدم تحریف قرآن
- نصوص اور ظواہر قرآن کی حجیت
- حجیت ظواہر کے دلائل
- 1- ارتکاز عقلا
- 3- وضع الفاظ
- حجیت ظواہر قرآن اور اخباری مسلک
- سنت
- سنت رسول کی حجیت
- سنت ائمه علیهم السلام کی حجیت
- 5- تعریف سنت
- 6. - سنت نبوی کی حجیت
- 7- سنت اہل بیت کی حجیت
- پهلی آیت آیه تطهیر
- دوسری آیت آیه اولی الامر ہے
- 8- سنت اہل بیت کی حجیت
- سنت اہل بیت کی حجیت پر چند شبهات
- پهلا اعتراض
- جواب
- دوسرا اشکال
- جواب
- توضیح مطلب
- تیسرا اشکال
- جواب
- فعل معصوم سے استنباط کی کیفیت
- تقریر معصوم کی حجیت کیسے ثابت ہوگی ؟
- سنت صحابه
- 9- سنت صحابه کی حجیت پر دلیل نقل
- سنت تک پهنچنے کے راستے
- الف : سنت تک پهنچنے کے قطعی راستے
- 1- خبر تواتر
- اور خبر کی تیسری قسم
- 2- وه خبرواحد جو قرینه قطعیه کے ہمراہ ہو
- 3- اجماع
- 4- سیرۀ عقلاء
- 5- سیرۀمسلمین
- ب: سنت دستیابی حاصل کرنے سنت کے غیر قطعی راستے
- 1- خبرواحد
- روایت صحیح
- روایت حسن
- روایت ضعیف
- 1- شهرت
- الف: شهرت روائی
- ب:شهرت عملی
- ج: شهرت فتوائی
- کتاب و سنت کے مشترک مباحث ۔
- ادله نقلی کی تقسیمات ۔
- دلیل خاصل و عام ۔
- دلیل مطلق و مقید
- دلیل حاکم و محکوم
- دلیل وارد و مورد
- دلیل مجمل و مبین
- مفهوم و منطوق
- اقسام مفهوم
- ناسخ و منسوخ
- خبر واحد کے ذریعے نسخ کرنا ممکن نهیں
- حدیث کے ذریعه قرآن کی تخصیص و تقیید کا امکان
- جواب
- جواب
- اجماع
- ابن تیمیه کا کهنا ہے
- اجماع اہل سنت کی نظر میں
- 10- اجماع
- اجماع کی تعریف
- حجیت اجما ع پر قرآنی دلیل :(1) مترجم)
- 11- حجیت اجماع پرقرآن سے دلیل
- صورت استدلال
- استدلال کا جواب
- صورت استدلال
- جواب
- حجیت اجماع پر روایی دلیل
- مخالفین اجماع کا جواب
- اجماع امامیه کی نظر میں
- دلیل عقل
- توضیح مطلب
- گروه اول : اصحاب حدیث
- دوسرا گروه : اصحاب رائے
- دلیل عقلی فقهی منابع میں سے ایک منبع
- دلیل عقلی کی تعریف
- قوانین الاصول میں میرزا ی قمی کی تعریف
- تعریف صاحب فصول
- تعریف مرحوم مظفر
- عقل کے با ب میں تشیع کا مسلک تشیع د اور موقف با ب عقل
- مرحلهء اول
- مرحلهء دوم
- مرحله اول ،حکم عقلی کے موارد ومصادیق
- پهلامقام احکام عقلی کا احکام شرعی کے مبادی علل سے مربوط ہونا
- دوسرا مقام: احکام عقلی حکم شرعی کے دا ئرے میں
- تیسرا مقام: احکام عقلی احکام کا احکام کے نتائج احکام سے ارتباط
- مرحلهء دوم: دلیل عقلی کی حجیت کے دلائل
- دلیل عقل کی حجیت پر اشکالات
- 2-عقلی استدلال دو طرح ہیں
- جواب
- گروه اول
- گروه دوم
- قواعد فقهیه
- اصول عملیه
- یهاں پر دو نکته قابل توجه ہیں
- استنباط کے مورد اختلاف منابع
- قیاس (مترجم)
- 1 (مترجم) قیاس کی تعریف
- 2 (مترجم) قیاس کے ارکان
- 1- قیاس منصوص العله
- 2- قیاس اولویت
- 3- قیاس ہمراہ تنقیح مناط کے ساتھ
- قیاس مستنبط العله
- قیاس کی چوتھی قسم ککی ے دلائل حجیت کے دلائل پر نتقید
- جواب
- جواب
- جواب
- 15-نتیجهء بحث
- استحسان
- جواب
- مصالح مرسله
- 1- مصالح معتبره
- 2- مصالح ملغی
- 3- مصالح مرسله
- جواب
- سد و فتح ذرایع
- 16- ذرایع کی قسمیں اور انکا حکم
- الف - قرافی تقسیم
- ب- ابن قیّم کی تقسیم
- 17- سد ذرایع کی حجیت کی دلیلیں
- تعارض ادله
- عرف
- عرف کی تقسیمات
- 1- عرف خاص اور عرف عام
- عرف عام
- 2- عرف عملی اور عرف قولی
- عرف قولی
- عرف صحیح اور عرف فاسد
- عرف فاسد
- مذاہب اسلامی میں عرف کی حجیت
- عرف کی حجیت کے دلایل اور ان کا جواب
- جواب
- جواب
- فهرست منابع اور ماخذ






