اٹھار ہواں سبق
پرور دگار کی عظمت و جلالت کا احترام
*قرآن مجید اور احادیث میں ذکر الٰہی کی اہمیت
*ذکر کی کمیت و کیفیت
*لفظی و قلبی ذکر کے درمیان رابطہ
*لفظی ذکر کے دو فائدے
پروردگار کی عظمت و جلالت کا احترام
''یَا اَبَاذَرٍ! لِیَعْظُمْ جَلاَلَ ﷲ فِی صَدْرِکَ فَلا تَذْکُرُهُ کَمٰایَذْکُرُهُ الْجَاهِلُ عِنْدَ الْکَلْبِ َاللَّهُمَّ اخْزِهِ وَعِنْدَ الْخَنْزِیرِ اَللَّهُمَّ اخْزِهِ''
''اے ابوذر! پرور دگار کی عظمت و جلالت تمھارے دل میں بڑھ جائے اسے ہلکا نہ سمجھنا، جیسے جاہل اور نادان لوگ جب کتے اور سور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں: خدا وندا! ان کا گلا گھونٹ دے۔''
قرآن مجید اور احادیث میں ذکر الٰہی کی اہمیت:
حدیث کے اس حصہ میں موضوع سخن خدا کی یاد اور اس کی عظمت کی تجلیل و احترام ہے۔ قرآن مجید اور روایتوں میں خدا کی یاد کو فراوان اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک بعض موضوع جیسے ذکر الہٰی کی تشویق، ذکر کے دنیوی و اخروی فائدے، ذکرکی کمیت و کیفیت، ذکر کے لئے زمان ومکان جیسے عناوین سے روایات میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح زبانی اور قلبی ذکر کے بارے میں ، یہ کہ ان میں سے کون اہم و برتر ہے یا یہ کہ ذکر خلوت و تنہائی میں بہتر ہے یا ملائ(مجمع) عام میں ، ان سب کے بارے میں بھی اہل بیت علیہم السلام اور علمائے دین کی طرف سے بیان ہوا ہے۔
حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا ہے:
''ما اجتمع قوم فی مجلس لم یذکروااللّٰه ولم یذکرونا الاکان ذٰلک المجلس حسرة علیهم یوم القیامة''
''کوئی قوم یا افراد کسی مجلس میں جمع نہیں ہوںگے کہ جس میں خدا کی یاد اور ہمارا تذکرہ زبانوں پر جاری نہ ہو، مگر یہ کہ وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے حسرت و اندوہ کا باعث ہوگی۔''
نیز فرمایا:
''اِنَّ ذکر نامن ذکر ﷲ''
ہماری یاد بھی خدا کی یاد ہے۔
ذکر اور خد کی طرف توجہ کی اہمیت کے پیش نظر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
جب کسی مجلس سے اٹھو تو ان آیات کی تلاوت کرنا:
(
سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَسَلاَم عَلَی الْمُرسَلِینَ وَالْحَمْدُ ﷲِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
)
(صافات ١٨٠، ١٨٢)
آپ کا پرور دگار جو مالک عزت بھی ہے ان کے بیانات (توصیف) سے پاک و پاکیزہ ہے۔
اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے۔ اور ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔
اس بنا پر انسان کو ہمیشہ دل و زبان پر ذکر خدا کو جاری رکھنا چاہئے اور اس ذکر کے لئے زمان و مکان یا کوئی خاص مجلس مخصوص نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:
خدا وندا! بعضمواقع اور حالات میں شرماتا ہوں کہ تیرے ذکر کو زبان پر جاری کروں اور تجھے یاد کروں۔ خدائے متعال نے فرمایا: میرا ذکر ہر حالت میں اچھا ہے۔
یاد اور ذکر الہٰی کے لئے یہ سب نصیحت اور تاکید انسان کو رذائل اور اخلاقی کو تاہیوں سے بچانے اور اسے سعادت و خوشبختی کی منزل تک پہنچانے کے پیش نظر کی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں ڈوبا ہوا اور ہمہ وقت خود کو خدا کے حضورمیں تصورت کرے، تو ایسے امور سے پرہیز کرے گا جو خداکو پسند نہیں ہیں اور اپنے نفس کو سرکشی سے روکے گا۔
تمام مشکلات اور خطائیں جو نفس امارہ اور شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں' خدا کی یاد اور اس کے عذاب سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا سے غفلت اور بے توجہی دل کو تاریک بنا دیتی ہے' جس کے نتیجہ میں نفسانی خواہشات کا انسان پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں خدا کی یاد اور اس کا ذکر دل کو پاکیزگی بخشتا ہے اور روح کی پاطہارت اور رزائل سے دور ہونے کا ذریعہ ہے اور انسان کو نفس کی قید سے آزاد کرتاہے۔ اس صورت میں انسان کا دل پروردگار کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے اور دنیا پرستی۔ جو تمام خطاؤں اور انحرافات کا سرچشمہ ہے۔ دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں:
''وَ اعْلَمُو اَنَّ خَیْرَ اَعْمَالِکُمْ (عِندَ مَلِیکِکُمْ) وَاَزْکَاهَا وَ اَرْفَعَهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ خَیْرَمَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ ذِکْرُ ﷲ سُبحٰانَه وَ تَعٰالیٰ فَاِنَّه اَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: اَنَا جَلیسُ مَنْ ذَکَرَ نِی''
جان لو خدا کے نزدیک تمہارے بہترین اعمال' ان میں سے پاکیزہ ترین اور بلند ترین تمھارے درجات اور بہترین چیز جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے خدا وند سبحان کا ذکر ہے۔ کیونکہ خدائے متعال اپنے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ اور فرماتا ہے: میں اس کا ہمنشیں ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔
ایک دوسرے روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
''اِنَّ ﷲ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ: مَنْ شُغِلَ بِذِکْرِی عَنْ مَسْاَلَتِی اَعْطَیتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِیَ مَنْ سَاَلَنی''
خدائے متعال فرماتا ہے: جو میری یاد اور میرے ذکر میں مصروف رہنے کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کر سکے'میں اسے اس سے بہتر عطا کروں گا جس کو میں سوال کے ذریعہ عطاکرتا ہوں۔
خدائے عزوجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:
''یا عیسیٰ اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی واذکرنی فی ملاک اذکرک فی ملا خیر من ملا الادمیین. یا عیسیٰ الِنْ لیقلبک و اکثر ذکری فی الخلواٰت واعلم ان سروری ان تبصبص الیَّ وکن فی ذٰلک حیا ولا تکن میتا''
اے عیسیٰ! تم مجھے اپنے پاس یاد کرو تاکہ میں تمھیں اپنے نزدیک یاد کروں اورتم مجھے لوگوں کے درمیان یاد کرو' تاکہ میں بھی تجھے انسانوں سے بہتر جماعت (فرشتوں) میں یاد کروں ۔ اے عیسیٰ: اپنے دل کو میرے لئے نرم کرو اور تنہائیوں میں مجھے زیادہ یاد کرو اور جان لو کہ میری خوشی اس میں ہے کہ میرے لئے تواضع کرو اس کام کیلئے اپنے دل کو زندہ رکھو اور مردہ (افسردہ) نہ رہو''
خدا کی یاد کے بارے میں قرآن مجید کی تاکید اور توجہ اس حد تک ہے کہ اس میں نماز کے مقصد کو خدا کی یاد کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں نماز کی منزلت بلند ہے اور اسے دین کے ستون کی حیثیت سے پہچانا گیا ہے۔
(...(
وَاَقِمْ الصَّلوٰةَ لِذِکرِی
)
(طہ١٤)
''اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو''۔
چونکہ مقصدوہدف وسیلہ سے زیادہ اہم ہوتا ہے' اس آیہ شریفہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ خدا کی یاداور اس کا ذکر نماز سے زیادہ اہم ہے اور حقیقت میں نماز' خدا کی یاد کا ایک وسیلہ ہے۔ (بیشک قرآن کی نظر میں ذکر کا ایک مفہوم اور اس کی ایک حقیقت ہے نماز تمام اہمیتوں کے باوجود اس کے لئے ایک وسیلہ سے زیادہ نہیں ہے)۔ قابل غور بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ نماز کے بعض اذکار قرآن کی آیات سے اخذ کئے گئے ہیں اور اس کی ایک خاص ہیئت و شکل ہے پھر کس طرح یہ خدا کی یاد کے لئے وسیلہ ہے؟
اس مطلب کی وضاحت میں کہنا چاہئے: نماز ایک خاص شکل و صورت'حرکات و سکنات اور اس میں پڑھے جانے والے اذکار کے باوجود ذکر شمار نہیں ہوتی بلکہ ذکر ایک قلبی کیفیت اور خاص توجہ کی حالت اور انسان کے دل کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کا نام ہے۔ لہذا نسان نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے اور خدا کے درمیان وہ خاص توجہ ا ور رابطۂ قلبی پیدا ہو جائے۔ اس بنا پر' نماز خود ایک وسیلہ ہے اور مقصد وہی توجہ اور قلبی ارتباط ہے جو بے شک نماز سے زیادہ محترم ہے۔
ذکر کی کمیت و کیفیت:
قرآن میں بیان کئے گئے منجملہ مسائل میں ذکر کی مقدار و کیفیت ہے۔قرآن مجید میں بعض آیات ذکر کی کمیت اور اس کی فراوانی پر تاکید کرتی ہیں' جیسے آیۂ:
(
یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُ وا ﷲ ذِکْراًکَثیراً
)
(احزاب٤١)
اے ایمان والو! اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔
(اس آیت میں ذکر کی زیادتی پر تاکید کی گئی ہے)
بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک حد معین کی گئی ہے' حتی نماز کے لئے بھی ایک حد معین ہے، ہر مکلف بالغ کے لئے دن رات میں پانچ مرتبہ سترہ رکعت نماز پڑھنا واجب ہے اور واجب نمازوں کے دو برابر نماز نافلہ پڑھنا مستحب ہے' یا یہ کہ ہر بالغ مسلمان کیلئے طاقت اور مالی استطاعت کی صورت میں عمر بھر میں ایک بار حج واجب کیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہر چیز کے لئے ایک حد مقرر ہوئی ہے' صرف خدائے متعال کی یاد اور اس کے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے۔ انسان جس قدر ذکر الٰہی کرے اور خدا کی یاد میں بسر کرے پھر بھی کم ہے۔
آیات و روایات کی پہلی قسم کے مقابلہ میں ' ذکر کی کیفیت کے بارے میں بہت سی آیات و روایات بیان ہوئی ہیں' من جملہ آیۂ:
(
فَاِذَا قَضَیْتُمْ مَنَاسِکَکُمْ فاذْکُرُوا ﷲ کَذِکْرِکُمْ آبَائَکُمْ اَوْ اَشَدُّ ذِکْراً
)
(بقرہ٢٠٠)
''پھر جب سارے مناسک تمام کر لو تو خدا کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی شدید تر...''
اس آیت میں ذکر خدا کے بارے میں نہیں فرماتا: ''واکثرذکراً' یعنی خدائے متعال کو زیادہ یاد کرو' بلکہ فرماتا ہے: خدائے متعال کوزیادہ شدت سے یاد کرو۔ پس یہاں پر ذکر کے کم و زیاد کے بارے میں بیان نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے ضعف و شدت کوبیان کیا گیا ہے۔ اور یہ لفظی اور زبانی ذکر سے مربوط نہیں ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ مثلاً ''لا الہ الا اللّٰہ ''کو غلیظ صورت میں تلفظ کیا جائے بلکہ یہ شدت اور ضعف' یاد اور توجہ قلبی سے مربوط ہے۔
علامہ طباطبائی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں:
''جاہلیت کے زمانہ میں عربوں کی یہ رسم تھی کہ اعمال حج بجالانے کے بعد منیٰ میں شعر و نثر کے ذریعہ اپنے آباء و اجداد کی ستائش کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے بعد خدائے متعال نے حکم دیا کہ اس رسم کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ذکرا ور یاد خدا بجا لائیں۔
اس آیت میں ذکر کی ''شدت'' کے طور پر توصیف ہو رہی ہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذکر مقدار کے لحاظ سے قابل افزائش ہے' کیفیت کے لحاظ سے بھی قابل شدت ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت میں ذکر لفظ میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک قلبی امر ہے جو حضور قلب سے انجام پاتا ہے اور لفظ اس کو بیان کرتا ہے۔''
بعض اوقات ہم ذکر کو لفظی ذکر میں منحصر جان کر' جب ذکر کی تاکید کی جاتی ہے تو ہم خیال کرتے ہیں ذکر ''الحمد للہ'' یا ''تسبیحات اربعہ'' وغیرہ کہنا ہے۔ جبکہ یہ سب کلمات ذکر کی حکایت کرتے ہیں اور حقیقت میں جس ذکر کی تاکید کی گئی ہے' وہ خدا کی یاد اور خدا کے بارے میں قلبی توجہ ہے۔ یعنی انسان فریضہ اور تکلیف انجام دیتے وقت خدا کی یاد میں غرق ہو جائے تا کہ خدا کے حضور کو درک کرتے ہوئے اپنا فریضہ انجام دے اور اسی طرح گناہ کو ترک کرتے وقت بھی خدا کی یاد میں ہو ' تاکہ اس کے حضور کا ادراک گناہ سے پرہیز کرنے کا سبب واقع ہو۔ ذکر لفظی کا ذکر قلبی سے اور لفظ کا معنی سے رابطہ' میوہ کے چھلکے کا اس کے مغز کے ساتھ رابطہ کے مانند ہے۔ حقیقت میں لفظی ذکر قلبی ذکر کا ایک لباس ہے اور قلبی ذکر اس کا مغز ہے۔ لہذا لفظی اذکار' قلبی اور داخلی یاد اور ذکر کا مقدمہ ہے اور یقیناً ان کی طرف توجہ کی جانی چاہئے۔ اس لحاظ سے روایتوں میں اذکار کی مقدار اور مواقع مشخص ہوئے ہیں' مثال کے طور پر نماز کے بعد بعض اذکار تعقیبات کے عنوان سے متعین ہوئے ہیں۔
لفظی و قلبی ذکر کے درمیان رابطہ:
یہاں پر مناسب ہے لفظی ذکر کا قلبی توجہ کے ساتھ رابطہ کے بارے میں بیشتر وضاحت کی جائے نیز بیان کیا جائے کہ کیوں ذکر کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے یہاں تک اسے نماز کے مقصد کے طورپر بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی سعادت اور تکامل میں ذکر کا کیانقش ہے؟ کیا جو ذکر نہیں کرتے اور خدا کی طرف قلبی توجہ نہیں رکھتے ہیں اپنی زندگی میں نقصان اٹھاتے اور شکست کھاتے ہیں؟
جب ہم بات کرتے ہیں اور کوئی چیز زبان پر لاتے ہیں تواس سے پہلے اپنے دل میں اس کے معنی کا تصور کرتے ہیں اور ہماریے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتاہے کہ اپنا مطلب دوسروںکو سمجھا دیں۔ عام طور پر بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مقصود اور منظور کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے' اگرچہ بعض اوقات گفتگو اور بات کرنے کا مقصد معنی کو منتقل کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ خاص نفسانی مسائل یا تلقین مد نظر ہوتی ہے۔
ماہرین نفسیات اور نفسیاتی طبیبوں کے کام کے بارے میں ان کی ایک نصیحت یہ ہے کہ جس پر وہ بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں تلقین ہے' البتہ اس کے لئے خاص الفاظ و آداب کو مد نظر رکھا گیا ہے' تاکہ تلقین موثر واقع ہو۔ مثال کے طور پر کہا گیا ہے: ایک خلوت میں بیٹھ کر ایک معین حد تک آواز بلند کر کے چند مرتبہ ایک جملہ کی تکرار کیجئے' تاکہ تمہاری روح میں یہ جملہ اثر کرے۔ یہ استثنائی مواقع ہیں' غالباً انسان بات کرتے وقت ایک معنی کو تصور کرتا ہے' اس کے بعد لفظ کے ذریعہ اسے دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ ایک عاقل انسان کبھی معنی کو مد نظر رکھے بغیر بات نہیں کرتا ' کیونکہ کلمہ یا لفظ معنی کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔
لفظی ذکر کہتے وقت' مثلاً ''تسبیحات اربعہ'' کہتے وقت ہم ایک معنی کو تصور کرتے ہیں اور اس کلمہ کو تصور کئے گئے معنی کو بیان کرنے والا قرار دیتے ہیں' ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس معنی کو ہم خدائے متعال یا ملائکہ اور دوسروں کو سمجھادیں' کیونکہ یہاں پر ہم مکالمہ اور گفتگو کا قصد نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ معنی ہماری روح میں اثر کرے۔ لہذا اثر معنی میں ہے اور کلمہ وسیلہ کے علاوہ کچھ نہیںہے۔
جب ہم ''اللہ اکبر'' کہتے ہیں اور اس ذکر کو ایک مقدس عمل کے طور پر قبول کرتے ہیں' ہمارا مقصد اس ذکر کے معنی کا انسان کی روح اور سعادت پر اثر ڈالنا ہے ورنہ کلمات اور حروف (الف 'لام'کاف) معنی کو نظر انداز کرنے کی صورت میں خود سے نکلنے والی ایک آواز ہے جس میں کوئی اثر نہیں' اس لحاظ سے ذکر کے وقت با معنی کلام بیان کرنا چاہئے۔
نتیجہ کے طور پر لفظی ذکر بیان کرنے سے پہلے انسان میں خدا کی یاد کا ایک ادنی مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد خدا کی یاد کا ایک عالی مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ابتداء میں خدا کو یاد کرتا ہے (ورنہ اگر خدا سے بالکل غافل ہو تو ذکر کرنے کا مرحلہ ہی نہیں آتا ہے) انسان کی توجہ جتنی بھی کمزور ہو' ذکر سے قبل خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اس کے بعد ذکرکرتا ہے جو خدا کی یاد کی دلیل ہے۔ پس لازمی طور پر ذکر سے پہلے خدا کی یاد کا ایک مرتبہ ہم میں موجود ہوتا ہے۔
لفظی ذکر کے دو فائدے:
لفظی ذکر کا پہلا فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ خدا کی یاد کا ضعیف مرتبہ قوی ہو جاتا ہے تاکہ انسان کی توجہ خدا کی طرف متمرکز ہو جائے۔ انسان کے اندر ابتدا میں خدا کے لئے ایک مبہم توجہ ہوتی ہے یا اس کی توجہ منتشر ہوتی ہے لیکن لفظی ذکر خاص کر نماز کے ذریعہ' وہ توجہ قوی اور متمرکز ہو کر خدا کی سمت میں معین ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مقصد اور فائدہ ہے جسے لفظی ذکر کے بارے میں تصور کیاجا سکتا ہے۔
لفظی ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر لفظی ذکرسے وہ ضعیف توجہ قوی نہیں ہوتی تو کم از کم اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا۔ انسان کے حالات اور اس کی توجہات' منجملہ خدا کی یاد ہمیشہ متغیر اور زوال پذیری کے خطرہ سے دو چار ہے۔ اس لحاظ سے اس کی قلبی توجہ کے استمرار کیلئے لفظی ذکر سے مدد حاصل کرنی چاہئے' تاکہ خدا کی یاد ہم سے فراموش نہ ہو جائے۔ اس بنا پر ذکر کیلئے مذکورہ دو فائدے اور مقصد شمار کئے جا سکتے ہیں' لیکن پہلا فائدہ اور مقصد بہتر اور عالی تر ہے۔
بعض اوقات ممکن ہے لفظی ذکر کا کوئی فائدہ نہ ہو' اور وہ اس صورت میں ہے جب ذکر کو بہ عنوان عادت ورد کیا جائے اور صرف زبان کی حرکت ہو اور انسان اس کے معنی کی طرف توجہ نہ رکھے۔ تمام زبانی عادات اور اعمال کی طرح کہ انسان کسی قسم کی توجہ کے بغیر زبان سے اس کا ورد کرتا ہے۔ بعض لوگ ہمیشہ تسبیح گھماتے رہتے ہیں ، تسبیح ا ور اس کے فائدہ کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ یا بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں یا داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں اور اس کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ زبانی عادت کے بارے میں بعض بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بعض کلمات کو زبان پر جاری کرتے ہیں' بغیر اس کے کہ اس کی طرف ان کا قلبی میلان ہو۔
ہم میں سے بہت سے لوگ بعض دعاؤں اور اذکار کو ایک خشک عادت کے طور پر پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے معنی و مفہوم کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے' اس لحاظ سے ان دعاؤ ںکے ذریعہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے ہم ابتداء میں توجہ کے ساتھ کسی کام کو شروع کریں اور کسی ذکر کو زبان پرجاری کریں' مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ تسبیحات فاطمہ زہر اسلام اللہ علیہا یا فلاں ذکر کابہت زیادہ ثواب ہے' اس لحاظ سے اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہماری توجہ کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک ان کلمات کو بہطور عادت کسی قسم کی توجہ کے بغیر زبان پر جاری کرتے ہیں۔ البتہ ''اللہ اکبر' ''لا الہ الا اللہ'' جیسے اذکار کو توجہ کے بغیر بھی کہنا مہمل اور بیکار کی باتوں سے بہتر ہے لیکن یہ انسان میں مطلوب روحانی اثر پیدا نہیں کرتے۔
ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو خدا پر کسی قسم کا اعتقاد نہیں رکھتے لیکن عادت کے طور پر خدا کا نام زبان پر جاری کرتے ہیں اور یہ کام ان کیلئے ایک ثقافت اور تہذیب کا حصہ بن گیا ہے، اس سے پہلے بعض کمیونسٹ جو دین' معنویات اور خدا پر بالکل اعتقاد نہیں رکھتے تھے' لیکن رسم اور عادت کے مطابق جب ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے تھے' ایک دوسرے کے احترام میں ''خدا حافظ'' کہتے تھے لیکن وہ اس کے معنی پر کوئی توجہ نہیں کرتے تھے' چنانچہ بعض اوقات ہم مسلمانوں میں بھی خدا کا نام زبان پر جاری کرنا رسم و عادت بن گئی ہے اور اس کے معنی و مفہوم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔
عصر جاہلیت کے عربوں اور اس طرح صدر اسلام کے عربوں میں جو تازہ اسلام لائے تھے۔ اللہ کا نام زبان پر جاری کرنا مرسوم تھا۔ جب وہ کسی کتے یا سور کو دیکھتے تھے تو نفرت کے طور پر کہتے تھے ''اللھم اخزہ'' خدایا اسے نابود کر۔ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کی یاد کی طرف کوئی قلبی توجہ کرتے۔ بیشک یہ کلمات انسان میں کسی قسم کا اثر نہیں ڈالتے اور یہ خدا کی یاد شمار نہیں ہوتے ہیں۔
اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جناب ابوذر سے تاکید کرتے ہیں کہ جب خدائے متعال کو یاد کرنا چاہو تو پہلے اس کی عظمت و جلال کا تصور کرو۔ یاد رکھو کہ جو خدا وند تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام چیزیں اس کی قدرت میں ہیں' جس طرح بے انتھا عظمت و جلال کا مالک ہے اس کا نام بھی بے انتہا عظمت و جلال کا مالک ہے' اس جہت سے اس کی عظمت و کبریائی کا تصور کرو۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب تمھاری روح اور دل میں خدائے تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوجا ئے' تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا نام زبان پر جاری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جاہل لوگوں کی طرح جو کسی توجہ کے بغیر خدا کا نام زبان پر لیتے ہیں عادت کے طور پر خدا کا نام زبان پر جاری کرو۔
وہ ذکر انسان کی روح ونفس پر اثر کرتا ہے'جو ذکر نماز قائم کرنے میں اطمینان قلب اور مقصد شمار ہوتا ہے' وہ ذکر انسان کی روحی و معنوی بلندی کا سبب اور دنیوی و مادی افکار کو چھوڑنے کا باعث نیز ابدی آخرت اور خدا کی نعمتوں کے وسیع ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے جو انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ مستحکم اور مضبوط کرے ' جو اس کے معنی و مفہوم کو ملحوظ رکھ کرنیز خدائے متعال کو حاضر و ناظر سمجھ کر زبان پر جاری ہوتا ہے۔ یہ وہی ذکر ہے جس کی توصیف میں خدائے متعال فرماتا ہے:
(
اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِینَ اِذَاذُکِرِ ﷲ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
)
(انفال٢)
بیشک مومنین وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز نے لگتے ہیں
آخرمیں مناسب ہے کہ بعض اصحاب پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
کے ذکرا ور یاد خدا کی مقدار کی توصیف کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے کلام کا ملا حظہ کریں:
''...لقدرأیت اصحاب محمد صلی ﷲ علیه و آله وسلم فما اَریٰ احداً منکم یشبههم' لقد کانوا یصبحون شُعثاً غُبَراً وقد باتوا سُجداً و قِیَاماً یُراوحُونَ بین جِبٰاهِهِم وخُدودِهِم و یَقِفون علی مثل الْجمر من ذکر مَعٰادهم کأَنَّ بین اعیُنِهم رکب المِعزیٰ من طول سجودهم
...''
میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ان کے مانند ہوگا۔ وہ صبح سویرے بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود ہوتے تھے کیونکہ وہ رات بھر قیام و سجود کی حالت میں بیدار رہتے تھے، گاہے اپنی پیشانی کو اور گاہے اپنے رخسار کو خاک پررکھتے تھے۔ قیامت کی یاد میں چنگاری اور آگ کے شعلے کی طرح جلتے ہوئے کھڑے رہتے تھے (اضطراب و پریشانی کی شدت سے) گویا ان کی پیشانیوں پر طولانی سجدوں کے سبب بکریوں کے زانوؤں کے مانند گھٹے پڑجاتے تھے۔
____________________
 4%
4%
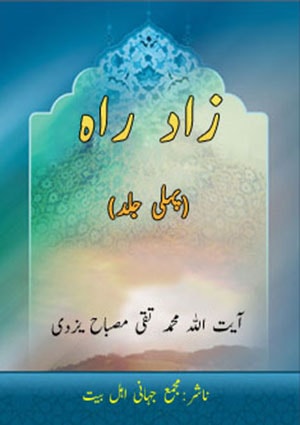 مؤلف: آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی
مؤلف: آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی





