اسلامی نظریہ حکومت
 21%
21%
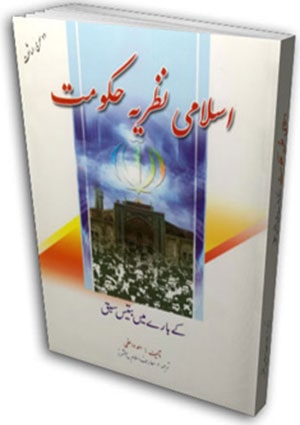 مؤلف: علی اصغر رضوانی
مؤلف: علی اصغر رضوانی
زمرہ جات: متفرق کتب
صفحے: 367
- پہلا باب
- دين اور سياست
- تمہيد
- پہلا سبق
- سياست اور اس كے بنيادى مسائل
- علم سياست اور سياسى فلسفہ(۱)
- خلاصہ
- سوالات
- دوسرا سبق
- اسلام اور سياست
- سياست ميں اسلام كے دخيل ہونے كى ادلّہ
- اسلام كا سياسى فلسفہ اور سياسى فقہ
- سبق كا خلاصہ
- سوالات
- تيسرا سبق
- دينى حكومت كى تعريف
- حكومت اور رياست كے معاني
- دينى حكومت كى مختلف تعريفيں
- مذكورہ چار تعريفوں كا مختصر تجزيہ
- خلاصہ
- سؤالات
- چوتھا سبق
- سياست ميں حاكميت دين كى حدود
- حكومت اور اس كے سياسى پہلو
- حاكميت دين كى حدود
- خلاصہ
- سوالات
- پانچواں سبق
- دينى حكومت كے منكرين
- سياست سے اسلام كى جدائي
- دينى حكومت كا تاريخى تجربہ
- خلاصہ
- سوالات
- چھٹا سبق
- سيكولرازم اور دينى حكومت كا انكار
- سيكولرازم كى تعريف
- دين اور سيكولرازم
- خلاصہ
- سوالات
- ساتواں سبق
- دينى حكومت كى مخالفت ميں سيكولرازم كى ادلہ -۱-
- پہلى دليل
- اس پہلي دليل كا جواب
- خلاصہ
- سوالات
- آٹھواں سبق
- دينى حكومت كى مخالفت ميں سيكولرازم كى ادلّہ -۲-
- دوسرى دليل
- اس دوسرى دليل كاجواب
- خلاصہ
- سوالات
- دوسرا باب
- اسلام اور حكومت
- تمہيد
- نواں سبق
- آنحضرت (ص) اور تاسيس حكومت -۱-
- حكومت كے بغير رسالت
- پہلى دليل كا جواب
- دوسرى دليل كا جواب
- خلاصہ
- سوالات
- دسواں سبق
- آنحضرت (ص) اور تأسيس حكومت -۲-
- جابرى كے نظريئےکا جواب
- آنحضرت (ص) كى حكومت كا الہى ہونا
- خلاصہ
- سوالات
- گيا رہواں سبق
- آنحضرت (ص) كے بعد سياسى ولايت
- اہلسنت اور نظريہ خلافت
- خلاصہ
- سوالات
- بارہواں سبق
- شيعوں كا سياسى تفكر
- زمانہ غيبت ميں شيعوں كا سياسى تفكر
- خلاصہ
- سوالات
- تيرہواں سبق
- سياسى ولايت كى تعيين ميں بيعت اور شورى كا كردار -۱-
- بيعت كا مفہوم اور اس كى اقسام
- نظريہ انتخاب كى مؤيد روايات
- صدور روايات كا زمانہ اور ماحول
- خلاصہ
- سوالات
- چودہواں سبق
- سياسى ولايت كى تعيين ميں بيعت اور شورى كا كردار -۲-
- ان روايات كے جدلى ہونے كى دليليں
- خلاصہ
- سوالات
- تيسرا باب
- ولايت فقيہ كا معنى ، مختصر تاريخ اور ادلّہ
- تمہيد
- پندرہواں سبق
- ولايت فقيہ كا معني
- ولايت كى حقيقت اور ماہيت
- اسلامى فقہ ميں دوطرح كى ولايت
- خلاصہ
- سوالات
- سولہواں سبق
- فقيہ كى وكالت اور نظارت كے مقابلہ ميں ولايت انتصابي
- ولايت انتصابى اور وكالت ونظارت ميں فرق
- خلاصہ
- سوالات
- ستر ہواں سبق
- ولايت فقيہ كى مختصر تاريخ -۱-
- خلاصہ
- سوالات
- اٹھارہواں سبق
- ولايت فقيہ كى مختصر تاريخ-۲-
- خلاصہ
- سوالات
- انيسواں سبق
- ولايت فقيہ، كلامى مسئلہ ہے يا فقہى ؟
- كسى مسئلہ كے كلامى يا فقہى ہونے كا معيار
- ولايت فقيہ كا كلامى پہلو
- خلاصہ
- سوالات
- بيسواں سبق
- ولايت فقيہ كے اثبات كى ادلّہ- ۱ -
- فقيہ كى ولايت عامہ كا اثبات از باب حسبہ
- ولايت فقيہ كى ادلّہ روائي
- الف _ توقيع امام زمانہ (عجل الله تعالى فرجہ الشريف)(۱)
- خلاصہ
- سوالات
- اكيسواں سبق
- ولايت فقيہ كے اثبات كى ادلّہ -۲)
- ب: مقبولہ عمر ابن حنظلہ(۱)
- ج: مشہورہ ابى خديجہ
- خلاصہ
- سوالات
- بائيسواں سبق
- ولايت فقيہ كے اثبات كى ادلّہ -۳-
- ولايت انتصابى كے متعلق كچھ ابہامات كا جواب
- ولايت فقيہ كى تائيد ميں مزيدروايات
- ۱_ صحيحہ قدّاح
- ۲_ مرسلہ صدوق
- خلاصہ
- سوالات
- تيئيسواں سبق
- ولايت فقيہ پر عقلى دليل
- الف: عقلى محض ب: عقلى ملفّق
- ولايت فقيہ پر دليل عقلى محض
- دليل عقلى ملفق
- خلاصہ
- سوالات
- چوتھا باب
- دينى حكومت كى خصوصيات اور بعض شبہات كا جواب
- تمہيد
- چوبيسواں سبق
- فلسفہ ولايت فقيہ
- شرط فقاہت ميں تشكيك
- فقيہ كى سياسى ولايت كا دفاع
- خلاصہ
- سوالات
- پچيسواں سبق
- رہبر كى شرائط اور خصوصيات
- الف : فقاہت
- ب : عدالت
- ج : عقل ،تدبير ، قدرت ، امانت
- فقہ ميں اعلميت كى شرط
- خلاصہ
- سوالات
- چھبيسواں سبق
- رہبر كى اطاعت كى حدود
- نظام ولايت ميں رہبر كا مقام
- مخالفت كى اقسام
- الف : مخالفت عملى ب : مخالفت نظري
- ولى فقيہ كى مخالفت كا امكان
- خلاصہ
- سوالات
- ستائيسواں سبق
- حكومتى حكم اور مصلحت
- حكم كى اقسام
- الف : شرعى حكم
- ب: قاضى كا حكم
- ج: حكومتى حكم
- حكومتى حكم كے صدور كى بنياد
- احكام اوّليہ اور ثانويہ
- خلاصہ
- سوالات
- اٹھائيسواں سبق
- حكومتى حكم اور فقيہ كى ولايت مطلقہ
- فقيہ كى ولايت مطلقہ
- خلاصہ
- سوالات
- انتيسواں سبق
- دينى حكومت كے اہداف اور فرائض -۱-
- حقيقت حكومت از نظر اسلام
- دينى حكومت كے اہداف
- الف: معنوى اہداف
- خلاصہ
- سوالات
- تيسواں سبق
- دينى حكومت كے اہداف اور فرائض -۲-
- ب_ دنيوى اہداف
- دينى حكومت كے اہلكاروں كے فرائض
- ۱_ تقوى الہى كى رعايت
- ۲_ شائستہ قيادت
- ۳_زہد اور سادگى
- ۴_اجتماعى امور ميں مساوات
- ۵_لوگوں سے براہ راست رابطہ
- ۶_فقر كا خاتمہ اور ضروريات زندگى كى فراہمي
- خلاصہ
- سوالات
- اكتيسواں سبق
- دينى حكومت اور جمہوريت -۱-
- جمہوريت كى حقيقت
- اسلام اور جمہوريت كے در ميان ذاتى عدم توافق
- خلاصہ
- سوالات
- بتيسواں سبق
- دينى حكومت اور جمہور يت – ۲-
- دين اور جمہوريت كے درميان توافق كا امكان
- ولايت فقيہ اور جمہوريت ميں عدم توافق
- مذكورہ شبہہ كا جواب
- جمہوريت كى آفات
- خلاصہ
- سوالات
- ضميمہ جات
- ضميمہ نمبر۱
- سوال : كيا اہلسنت كے نزديك بھى ''ولايت فقيہ'' نام كى كوئي چيز ہے؟
- مختصر جواب
- تفصيلى جواب
- ضميمہ نمبر ۲
- سوال:ايسا معاشرہ جس ميں شيعہ ، غير شيعہ، مسلم اور غير مسلم افراد بستے ہيں اس ميں ولى فقيہ كے حكم كى حد ودكيا ہيں ؟
- مختصر جواب
- تفصيلى جواب
- حكم اور فتوى ميں فرق
- ولى فقيہ كے حكم كى حدود
- ضميمہ نمبر ۳
- سوال : ولى فقيہ كے ساتھ مسلمانوں كا رابطہ اور تعلق كس طرح كا ہونا چاہيئے؟
- مختصر جواب
- تفصيلى جواب
- رابطہ كى اقسام
- اصطلاحات






